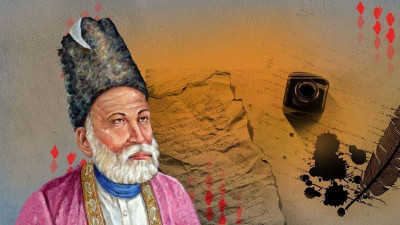تقسیم کا ادب اور تشدد کی شعریات
خواتین و حضرات! آج کی گفتگو کا موضوع ہے تقسیم کا ادب اور اس سے مرتب ہونے والی شعریات، جس کا شناس نامہ فرقہ وارانہ تشدد کے تجربے سے منسلک ہے۔ تشدد ہمارے زمانے کا غالب اسلوب ہے۔ بیسویں صدی کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ تشدد آمیز صدی کا نام دیا گیا ہے۔ اس صدی کی پیشانی پر، دو عالمی جنگوں سے قطع نظر، سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ تشدد، لسانی اور تہذیبی تشدد، علاقائی اور نسلی تشدد، جذباتی، اقتصادی اور نظریاتی تشدد کے بہت سے داغ بکھرے ہوئے ہیں۔
اس صور ت حال نے تشدد کے تجربے کو عام انسانوں کے لئے بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ لیکن ۱۹۴۷ء کی تقسیم کے ساتھ فرقہ وارانہ فسادات کے باعث تشدد کی جن صورتوں سے ہماری اجتماعی زندگی دوچار ہوئی، اس کے اثرات نہایت گہرے اور دیرپا ثابت ہوئے۔ بیسویں صدی کی جنگیں ہمارے لئے پرایا، یا دور کا تجربہ تھیں، لیکن ۱۹۴۷ء کی تقسیم کے نتیجے میں رونما ہونے والا تشدد ہمارے لئے ایک نجی واردات تھی۔ اسی لئے، اس المیے کا سایہ بھی ہماری ادبی، تہذیبی اور تخلیقی زندگی پربہت گہرا ثابت ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان کا ذہنی ماحول اب تک اس سایے کی گرفت میں ہے۔ ہمارے لیے تقسیم کا ادب اور اس ادب کی پہچان قائم کرنے والی شعریات، مطالعے کے ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں۔
۱۹۴۷ء جدید ہندوستان کی تاریخ اور ہماری اجتماعی زندگی میں منصوبہ بند دیوانگی، دہشت اور ابتری کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ بظاہر تقسیم کے نتیجے میں جوانسانی صورت حال رونما ہوئی اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت سے واقعات مبالغہ آمیز اور مہملیت کی حد تک غیر حقیقی دکھائی دیتے ہیں۔ جیتی جاگتی زندگی کی سطح پر جو سچائیاں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہماری معاشرتی فکر، ہمارے اعصاب سے اپنے ہونے اور دکھائی دینے (visibility) کی جو قیمت طلب کرتی ہیں، ان پربعض اوقات محض فرضی یا fictional ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تخیئلی اور تخلیقی سچائی کو، جو سامنے کے تاریخی اسباب اور عوامل کی پیدا کردہ ہے، دراصل کسی نادیدہ اور پراسرار تاریخ نے یا طاقت نے جنم دیا ہے اور اس کے واسطے سے ہماری اجتماعی زندگی کے ایک پورے سلسلے میں چھپی ہوئی سچائی سے پردہ اٹھایا ہے۔
سلمان رشدی نے اپنی ایک غیرافسانوی تحریر میں، ادب اور تاریخ کے تعلق کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارے شعور کی خفیہ اور نادیدہ تنہائیوں میں ادب کی حیثیت، اس ممنوعہ علاقہ کی ہوتی ہے جہاں ادیب کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن سے عام لوگ بے خبر گزر جاتے ہیں۔ دراصل انہی آوازوں کی مدد سے اس پر گردوپیش کی مرموز صداقتوں کے اسرار کھلتے ہیں اور وہ اپنی مانوس دنیا کے نامانوس گوشوں اور قریوں تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں ادب اور آرٹ کے تاریخی تناظر کا احاطہ کرتے وقت ایک ضروری بات جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے، یہ ہے کہ تاریخی سچائیاں چاہے جتنی ٹھوس ہوں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ظہور پذیر ہونے والی تاریخی صورت حال چاہے جتنی سخت گیر ہو، وہ تخلیقی عمل کی سمت اور رفتار کے تعین میں ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتی، نہ اس عمل کو روکنے میں کامیا ب ہو سکتی ہے۔
ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنے والا اپنی منفرد روحانی تلاش کے مطابق اپنے تخلیقی اور فنی مقاصد کی تلاش کرتا ہے اور اپنی الگ راہ نکالتا ہے۔ بڑے ادبی شہ پاروں میں ذہنی کشمکش اور اضطراب یا اندرونی پیچ و تاب کے نشانات جو نمایاں ہوتے ہیں، تو اسی لئے کہ ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنے والے کا بنیادی سروکار تاریخی شعور کی افزائش سے نہیں ہے، اس کااصل کام تو مروجہ شعور پر غلبہ حاصل کرنا اور اس سے بچ کر اپنی راہ نکالنا ہے۔ ہماری اجتماعی تاریخ کے حوالے سے اٹھارہویں صدی کی اتھل پتھل کے دوران میر صاحب کا ردعمل، یا انیسویں صدی کی نشاۃ ثانیہ اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی وہ پرچھائیاں جو غالب کے تخلیقی شعور اور حسیت کی نشاندہی کرتی ہیں، ان سب سے اسی سچائی کا اظہار ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر غالب بظاہر تاریخ کی منطق کو سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وقت کی تقویم میں ماضی صرف ماضی ہے اور ہر عہد، بہرحال اپنے ایک الگ آئین کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے عہد میں ماضی اور حال کی مسلسل کشمکش کے باعث اپنے باطنی پیچ وتاب سے وہ کبھی دامن نہ بچا سکے۔ انہوں نے اس تمام صورت حال کو تخلیقی سطح پر جس طرح قبول کیا، وہ عام ذہنی سطح کی بہ نسبت بہت پیچیدہ اور مختلف ہے۔ اس سطح کے گرد ماضی کا حصار کھنچا ہوا ہے۔ اس سے صرف ان کے حال میں پیوست سچائیوں کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ ان کے حال پر یوں بھی ان کا تہذیبی ماضی ہمیشہ حاوی رہا اور گردوپیش کی تبدیلیوں سے وہ کبھی مطمئن نہ ہوئے،
مراشمول ہر اک دل کے پیچ وتاب میں ہے
میں مدعا ہوں تپش نامہ تمنا کا
یا یہ کہ،
ہوں میں بھی تماشائی نیرنگ تمنا
مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی برآوے
بے شک ۱۸۵۷ء بہ قبول عرفان حبیب نہ صرف تاریخ ہند کا بلکہ عصر جدید کی تاریخ کا بھی ایک بڑا واقعہ تھا اور اس واقعے کی تہذیبی، سیاسی، معاشرتی جہتیں کثیر تھیں لیکن غالب نے شاعری میں اس واقعے کو ایک ذاتی واردات کے طور پر قبول کیا تھا۔
۱۹۴۷ء اور تقسیم کے ساتھ ہماری اجتماعی تاریخ میں جو واقعات رونما ہوئے، ان کی نوعیت بھی ۱۸۵۷ء کے بعد کے ہندوستانی معاشرے اور ماحول سے خاصی مماثل ہے۔ ۱۸۵۷ء کی طرح ۱۹۴۷ء کا ردعمل بھی ہماری تخلیقی اور ثقافتی زندگی پریکساں نہیں رہا۔ مختلف اشخاص نے مختلف زاویوں سے دیکھا اور اس کے الگ الگ معنی اخذ کئے۔ بہ ظاہر ہمارے زمان ومکاں تک محدو دہونے کے باوجود ۱۹۴۷ء کا واقعہ بھی ایک وسیع اور ہمہ گیر تناظر کی گنجائش رکھتا ہے۔ جذباتی، ذہنی اور معاشرتی سطح پر اس واقعے کے ساتھ جس طرح کے تجربے پیش آئے، ان کی گونج ہمیں دنیا بھر کے ادب میں سنائی دیتی ہے۔ انیتا اندر سنگھ نے اپنی کتاب (The Partition of India) اشاعت، نیشنل بک ٹرسٹ، دہلی ۲۰۰۶ء) میں تقسیم کے واقعے کو دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ طوفاں خیز اور انقلابی (cataclysmic) واقعوں میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ،
’’اٹھارہویں صدی سے لے کر اب تک یورپ، ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطی میں جو متعدد تقسیمیں ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک ۱۹۴۷ء کی تقسیم بھی ہے۔ اس تقسیم کے ساتھ بھی مختلف مذہبی گروہوں کے مابین تشدد اور فساد برپا ہوا۔ لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں ایسی کسی بھی دوسری تقسیم سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ ہندوستان کی تقسیم میں کتنے افراد مارے گئے، کتنے لوگ اجڑے اوربے گھر ہوئے (قطعی طور پر) کچھ پتہ نہیں، یہ تعداد دوسے لے کر تیس لاکھ تک کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ۱۹۴۶ء سے ۱۹۵۱ء کے درمیان لگ بھگ نوے لاکھ ہندوؤں اور سکھوں نے پاکستان سے ہندوستان کی سرحد میں قدم رکھا اور تقریبا ساٹھ لاکھ مسلمان ہندوستان سے پاکستان گئے۔۔۔‘‘
برطانوی سامراج کے سایے میں آئرلینڈ، فلسطین اور سائپرس کے علاوہ یہ چوتھی تقسیم تھی، اس بنیاد پر کہ مختلف قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کے بٹوارے کا صرف یہی سبب نہیں تھا۔ ان چاروں تقسیموں کے پیچھے برطانیہ کے فوجی مفادات کا ایک سلسلہ بھی تھا۔
انیتا اندر سنگھ نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا تقسیم سے متعلق اختلافات کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ اگر مختلف مذہبی اور تہذیبی قومیتیں ساتھ ساتھ نہ رہ سکیں تو کیا تقسیم کے ذریعے ان کامسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ تقسیم کی وکالت کرنے والوں کے نزدیک تقسیم ایک ذریعہ ہے تصادم کو قابو میں کرنے کا۔ لیکن کیا واقعی اس سے تصادم پر روک لگائی جا سکتی ہے؟ ۱۹۴۷ء کی تقسیم نے ایک کے دو ملک تو بنا دیے لیکن اجتماعی زندگی میں ایک عجب ابتری بھی پیدا کر دی۔ ہر تقسیم کی طرح ۱۹۴۷ء کی تقسیم نے بھی نے بین اقوامی سرحد کے دونوں طرف ایک مخلوط ثقافت اور جذباتی ماحول کو راہ دی ہے۔ ہماری تخلیقی روایت کے پس منظر میں کتنے ہی ذہنی میلانات، تجربات اور موضوعات اسی ماحول کی دین ہیں۔ لیکن ہر زمینی تقسیم کی طرح ۱۹۴۷ء کی تقسیم نے بھی سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور تخلیقی اعتبار سے متعدد نئے سوالوں کو جنم دیا ہے، جس کے اثرات ہندوستان اور پاکستان کے ادبی منظرنامے پر صاف دکھائی دیتے ہیں۔
تقسیم کے حامیوں کا خیال ہے کہ ایسی ہر تقسیم اپنی ایک منطقی بنیاد رکھتی ہے۔ ہر قوم کی ادبی اور تخلیقی روایت اس قوم کی ذہنی زندگی، عقائد، معاشرتی رسوم، جذباتی ترجیحات اور اسلوب زیست کی تابع ہوتی ہے۔ لہٰذا ۱۹۴۷ء کی تقسیم کے ساتھ ادبی اور تخلیقی لحاظ سے ایک طرح کے ذہنی اور جذباتی تضاد اور تصادم کی فضا تو پیدا ہونی ہی تھی۔ یہاں میں اس مسئلے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تاہم اس وقت اپنے موضوع گفتگو کی ضروریات کے پیش نظر اس کے بعض پہلوؤں کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ مثال کے طورپر ’’پاکستانی ادب کا مسئلہ‘‘ کے عنوان سے سلیم احمد نے اپنے معروضات کی ابتدا اس مقدمے کے ساتھ کی تھی کہ،
’’ادب کسی قوم کے مخصوص طرز احساس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ طرز احساس خدا، کائنات اور انسانوں کے بار ے میں اس قسم کے اجتماعی تجربات اور رویوں سے پیدا ہوتا ہے۔‘‘
پھر فرماتے ہیں، ’’لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کا طرز احساس ایک ہونے کے باوجود قوموں کے لحاظ سے اس طرز احساس کی مختلف شکلیں ہیں۔ عربی، ایرانی، ترکی اور ہندی مسلمانوں کا طرز احساس بنیادی طور پر ایک ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس اختلاف سے ان کے ادب کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔‘‘
اس مضمون میں سلیم احمد پاکستانی ادب کے مسئلے کو جس قدر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے موقف میں ژولیدگی اسی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ اس ژولیدگی کا نقطہ عروج ان کے اس بیان میں دکھائی دیتا ہے کہ، ’’ہمارے نزدیک اردو غزل کی مرکزی روایت میں خدا، کائنات اور انسانوں کے بارے میں ایک بالکل نیا طرز احساس ملتا ہے جو مسلمانوں کے شعروادب میں ایک منفرد چیز ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمانو ں کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک ہندو فراق کو اتنا شدید احساس ہے کہ ان کی ساری زندگی مسلمانوں کے طرز احساس سے لڑنے ہی میں گزر گئی۔‘‘
گویا کہ ۱۹۴۷ء کی تقسیم سے پہلے بھی اردو کے ہندو اور مسلمان شاعروں میں ان کی تخلیقی واردات اور طرز احساس کے حساب سے تقسیم کی ایک لکیر موجود تھی اور اس کا تعلق دونوں قوموں کے الگ الگ اسالیب زیست اور مجموعی تناظر سے تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ مفروضہ سرے سے غلط ہے اور اردو کی ادبی روایت کے سیاق میں اس کے جواز کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ امیر خسرو سے لے کر میر، مصحفی، آتش، غالب، بہادرشاہ ظفر، یگانہ، فانی، فراق یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء کے بعد نمایاں ہونے والے غزل گویوں مثلا ًناصر کاظمی اور احمد مشتاق تک، ان کے طرز احسا س کی بنیاد پر اگر کوئی خاکہ مرتب کرنا ہے تو ہندوستان کے سوال یا مذہبی تفریق اور تشخص کے سوال کو سرے سے الگ رکھنا ہوگا۔ یہ سب کے سب دراصل اس ہمہ گیر حسیت کے نمائندے ہیں جس کا تانا بانا ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ جستجو اور جدوجہد نے تیار کیا تھا۔
اس حسیت کی تعمیر میں دونوں قوموں کے بنیادی عقائد کا، فرقہ وارانہ قدروں کا، ضابطہ اخلاق اور روایت کا کوئی خاص رول نہیں ہے۔ اپنی ترکیب کے لحاظ سے یہ ایک سیکولر حسیت تھی اور اس کی تشکیل میں وہ عناصر سرگرم رہے تھے جن کا تعلق جمہوری زندگی سے ہے۔ اس لحاظ سے میر، غالب، فیض، فراق اور ناصر کاظمی، سب کے سب ایک ہی مالا کے منکے ہیں۔ ادوار کے فرق کے ساتھ، ان سب کے یہاں ایک سی معاشرتی فضا کا احساس ہوتا ہے۔
۱۹۴۷ء کی تقسیم کے آس پاس کا دور بے شک جذباتی، انتہا پسندی، بے قابو ہوتے ہوئے سیاسی اختلافات اور اپنے اپنے قومی یافرقہ وارانہ تشخص پر اصرار کا دور تھا۔ آزادی کے بعد فوراً کا زمانہ شدید ذہنی پراگندگی، ایک دوسرے کے تئیں بے اعتباری اور محدود وابستگیوں کا زمانہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی دہشت، دیوانگی، اعصابی تشنج اور اضمحلال کا دور تھا۔ ادب کے معاملے میں سیاست دانوں کی اکثریت اور حکومتیں تو خیر بالعموم احمق ہوتی ہیں لیکن تقسیم کے بعد کی فضا میں تو بہت سے ادیبوں کے لئے بھی اپنے ذہنی اور جذباتی توازن قائم رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس صورت حال نے پاکستان میں نسبتاً زیادہ پیچیدہ شکل اختیار کر لی تھی، علمی اور ادبی حلقوں میں ایک نئے تشخص کے قیام کو مرکزی مسئلے کی حیثیت دی جانے لگی تھی اور مختلف فکری گروہ اپنے اپنے طورپر اس کے مفہوم کا تعین اور اس کی تعبیر کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ایک پریشاں فکری کی کیفیت عام ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس دور میں لکھے جانے والے کچھ معروف مضامین سے یہ چند اقتباسات دیکھئے۔ پہلا اقتباس محمد حسن عسکری کی جون ۱۹۴۹ء کی ایک تحریر سے ہے،
’’ہمارے ادب میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر میں بھی منٹو صاحب کی اس رائے کا قائل ہو چلا ہوں کہ ابھی دس سال تک ہمارے ادب کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اگر ادیب خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بدل سکتی مگر اپنے آپ کو بدلے بغیر ادب میں تازگی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لئے پاکستان میں ادب کے مستقبل کے بارے میں خوش فہمیوں کی گنجائش ذرا کم ہے۔‘‘ (پاکستانی ادب، مشمولہ تخلیقی عمل اور اسلوب)
یہ دوسرا اقتباس جولائی اگست ۱۹۴۹ء کی ایک تحریر ہے، ’’زندگی کے شعبوں کی طرح ادب میں بھی اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کورد نہیں کر سکتے۔ ہر معاملے میں ہمارا ا ٓئندہ عمل بڑی حد تک ہمارے ماضی پر منحصر ہے، تو پاکستانی یا اسلامی ادب کی نئی روایت قائم کرنے کے لئے بھی ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں کے فنی کارناموں میں اسلامی روح کس طرح ظاہر ہوئی ہے۔‘‘ (پاکستانی قوم، ادب اور ادیب، حوالہ ایضاً)
یہ تیسرا اقتباس بھی عسکری صاحب ہی کے ایک مضمون، ’تقسیم ہند کے بعد‘ سے ہے، اس کی تاریخ اشاعت اکتوبر ۱۹۴۸ء ہے اور یہ اس لحاظ سے بہت معنی خیز ہے کہ اس سے تقسیم کے بعد ہندی مسلمانوں اور اردو سے ان کے تعلق کی بابت ایک ایسا موقف اختیار کیا گیا ہے جو تقسیم کے مجموعی طور سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ لکھتے ہیں،
’’اردو زبان سے عظیم تر کوئی چیز ہم نے ہندوستان کو نہیں دی۔ اس کی قیمت تاج محل سے بھی ہزاروں گنی زیادہ ہے۔ ہمیں اس زبان پر فخر ہے، اس کی ہندوستانیت پر فخر ہے اور ہم اس ہندوستانیت کو عربیت یا ایرانیت سے بدلنے کو قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اس زبان کے لب ولہجے میں، اس کے الفاظ اور جملوں کی ساخت میں ہماری بہترین صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں اور ہم نے مانجھ مانجھ کر اس زبان کی ہندوستانیت کو چمکایا ہے۔ اتنا کچھ کر چکنے کے بعد ہم اس پر ذرا بھی راضی نہیں ہیں کہ اس کے بجائے ہندی اختیار کر لیں یا ایک نئی زبان ’’ہندوستانی‘‘ ایجاد کریں اور پھر ایک سے گنتی شروع کریں۔ ہندوؤں کو اختیار ہے کہ وہ ہندی چھوڑ کر سنسکرت بولنے لگیں لیکن ہمارے لئے پھر سے عربی یا فارسی اختیار کر لینا ناممکن ہے۔ جس طرح ہمیں ہندی سے گریز ہے بالکل اسی طرح فارسی سے بھی گریز ہے۔ اگر ہم فارسی اختیار کربھی لیں تو ہندوستانی مسلمانوں کامخصوص کلچر باقی نہیں رہ سکتا۔ اردو کے علاوہ کوئی دوسری زبان اختیار کرنے کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماضی سے بالکل قطع تعلق کر لیا اور ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں۔ کوئی قوم ایسے تجربوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔‘‘ (جھلکیاں، ص ۳۳۳ تا ۳۳۴)
لگ بھگ اسی دور میں محمد حسن عسکری نے منٹو کے ساتھ مل کر مکتبہ جدید لاہور، کراچی کی طرف سے ’اردو ادب‘ کے دو شمارے شائع کئے تھے۔ اس وقت ادبی رسائل کی طرف حکومت کا رویہ سخت گیری کا تھا۔ ’اردوادب‘ کو باقاعدہ سرکولیشن کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اس لئے یہ دونوں شمارے کسی تاریخ کے حوالے کے بغیر منطرعام پر آئے۔ پہلے شمارے میں ’ہمارا ادبی شعور اور مسلمان‘ کے عنوان سے عسکری کا ایک مضمون شامل ہے، جس میں نئی آزاد مملکت کے قیام، اسے درپیش مسائل، اس مملکت کو سیاسی پس منظر مہیا کرنے والی سیاست کی طرف مسلمان ادیبوں کے رویے اور انداز نظر کے بارے میں کئی توجہ طلب باتیں کہی گئی ہیں۔ خاص کر اس اقتباس میں،
’’حقیقت یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے مسلمان ادیب اپنے عقائد، اپنے تصورات اور اپنے رجحانات میں مسلمان عوام سے بالکل الگ تھے۔ اب تک مسلمان ادیب اپنی قوم کی سیاست سے کم ازکم ذہنی ہمدردی ضرور رکھتے تھے۔ تخلیقی دلچسپی نہیں تھی تونہ سہی مگر اپنے ادیبوں کی غالب اکثریت کو مسلمانوں کے سیاسی عزائم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہت سے ادیب تومسلم لیگ کی سیاست کے سخت مخالف تھے اور بہت سے ادیب بالکل بے تعلق اور بےنیاز تھے۔ اسی طرح یا تو ادیب پاکستان کے مطالبے کے خلاف تھے یا پھر گومگو کی حالت میں تھے اور سمجھتے تھے کہ پاکستان بن جائے تو ہمیں کیا، نہ بنے توہمیں کیا۔ مذہب اور سیاست کا تعلق انہیں پسند تھا ہی نہیں۔ جن لوگوں کو اشتراکیت سے دلچسپی نہیں تھی، ان کابھی یہی حال تھا کہ سیاسی گتھیوں کا معاشی حل دوسرے سب حلوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ پھر یورپ کو تعریف کی نظروں سے دیکھنے کے لوگ ایسے عادی ہو چکے تھے کہ جو بات یورپ والوں کی عقل میں نہیں آ سکتی تھی، وہ ہمارے ادیبو ں کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔
چنانچہ بیسویں صدی میں کسی جماعت کا مذہبی اختلاف کی بنا پر سیاسی حقوق مانگنا انہیں بالکل ناقابل یقین معلوم ہوتا تھا۔ مگر چونکہ مسلم لیگ کو عوام کی اتنی زبردست حمایت حاصل تھی، اس لئے وہ اس مطالبے کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ ہمارے ادیبوں نے پاکستان کی نہ حمایت کی نہ کھل کر مخالفت ہی کی۔۔۔ ہمارے ادیب تو جیسے اپنے مستقبل کو قوم کے مستقبل سے وابستہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ غرض کہ اس دور میں ادیبوں نے اپنی حالت بھی عجیب معمے کی سی بنالی تھی۔ نہ تو اپنے آپ کو مسلمانوں سے بالکل الگ ہی کر سکتے تھے، نہ ان میں شامل ہی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس اندرونی تضاد کی وجہ سے بعض مسلمان ادیب بڑی مضحکہ خیز قسم کی ذہنی الجھنوں میں پڑگئے۔ کبھی کہا مسلم کلچر ہوتا ہے، کبھی کہا نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا کہ اردو عوام کی زبان ہے۔ کبھی خیال آیا کہ نہیں، محض ایک طبقے کی زبان ہے۔ پھر اوپر سے یہ فکر دامن گیر رہنے لگی کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے فرقہ پرستی کی بو آتی ہو۔ آزاد خیالی کی ایسی دھن سمائی کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے اٹکاہی نہیں رکھا۔ نہ کھل کے محبت کی نہ نفرت۔۔۔‘‘
۱۹۴۷ء اور ہندوستان کی تقسیم کے پس منظر میں لکھے جانے والے ادب کا غالب آہنگ تقسیم سے انکار کا ہے۔ ثقافتی بے جڑی کے احساس اور ڈھلمل یقینی کی ایک مستقل کیفیت نے اس دور کے تخلیقی ادب کو بالعموم ایک گہرے ملال، اضطراب اور محرومی کا ترجمان بنا دیا ہے۔ کچھ دنوں تک تو ایک ذہنی تعطل کی فضا قائم رہی۔ ہجرت، فسادات اور بے بسی کاسیلاب تھمنے کے بعد اپنے نظریاتی اور قومی تشخص کا سوال سامنے آیا۔ ا س سوال پر ٹھنڈے دل سے غوروفکر کی روایت تقسیم کے سانچے کے پانچ چھے برس بعد شروع ہوئی۔ غلام ربانی تاباں کی مرتب کردہ کتاب ’غم دوراں‘ میں تقسیم اور اس کے سایے میں رونما ہونے والے فسادات اور فرقہ وارانہ جنون کے موضوع پر اردو میں جو نظمیں کہی گئیں، ان میں خیال کی یکسانیت اتنی تھکا دینے والی اور بیان کی بے حجابی اس درجہ بیزار کرنے والی ہے کہ ان سے بالعموم کسی خاص ہنرمندی اور بصیرت کا اظہار نہیں ہوتا اور انہیں دل جمعی کے ساتھ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ جوش نے یہ کہتے ہوئے ان نظموں کا مذاق اڑایا تھا کہ،
آفریں برغلام ربانی
کیا نکالا ہے مینڈکوں کا جلوس
لیکن خود جوش صاحب نے فسادات کے پس منظر میں جو نظم کہی اس سے نہ تو کسی بڑے خیال کی تشکیل ہوتی ہے نہ کسی بڑے شعریات کی۔ اس نظم پر اعصابی تشنج اور جذبے کے اشتعال کا رنگ حاوی ہے۔ اس نظم سے کسی ایسے تجربے کا اظہار نہیں ہوتا جس کے لئے شعر کی ہیئت ناگزیر کہی جا سکے۔ پوری نظم کا اسلوب اور آہنگ ڈانٹ ڈپٹ کا ہے۔ جوش صاحب کی اس نظم کے علاوہ اسی موضوع پر اور اسی دور میں کہی جانے والی کچھ نظموں کے اقتباسات حسب ذیل ہیں،
اے ناقد تباہی و نباض روزگار
ہاں اس طرح بھی ایک نظر بہر کردگار
ہم ظلم کے ہیں شاہ شقاوت کے تاجدار
انسان ہے تو ڈال ہمارے گلوں میں ہار
ابلیسیت کا مرد ہے تو احترام کر
ہم ہیں امیرِ نادر و نیر و سلام کر
کس کس مزے سے ہم نے اچھالی ہیں عورتیں
سانچے میں بے حیائی کی ڈھالی ہیں عورتیں
شہوت کی بھٹیوں میں ابالی ہیں عورتیں
گھر سے برہنہ کرکے نکالی ہیں عورتیں
یہ لطف بھی کیے ہیں ہوس پروری کے بعد
پھاڑا ہے شرم گاہوں کو عصمت دری کے بعد
بوجہل کی شراب سے چھلکا کے جام کو
بٹا لگا دیا ہے محمد کے نام کو
زندہ کیا ہے راون ِدوزخ مقام کو
ہاں ہم نے روسیاہ بنایا ہے رام کو
قرآں کو ہم پہ فخر ہے ویدوں کو ناز ہے
سچ ہے حرام زادے کی رسی دراز ہے
جب تک کہ دم ہے ہندوو مسلم کے درمیاں
ہاں ہاں چھڑی رہے گی یونہی جنگ بے اماں
الجھی رہیں گی شام و سحر زیر آسماں
یہ چوٹیاں سروں کی یہ چہروں کی داڑھیاں
ہاں ہوش میں قتال کا بھنگی نہ آئےگا
جس وقت تک پلٹ کے فرنگی نہ آئےگا
یہ ایک شاعر کا یا تخلیقی آدمی کا کرب اور برہمی نہیں، ایک عام آدمی کا ا شتعال اور غم وغصہ ہے جونہ تو اپنے جذبات کی تہذیب پر قادر ہے، نہ اپنے اظہار کی بے لگامی پر۔ بیشک واردات بہت بڑی تھی اور بہت برانگیختہ کرنے والی، لیکن ہر فن کی طرح شاعری کے اپنے حدود ہوتے ہیں اور اپنی شرطیں۔ جوش نے ان اشعار میں جس شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے، اس سے ان کے انسانی سروکار، ان کی دردمندی اور ان کے تجربے کی سچائی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ شاعری صرف احساسات کو گرفت میں لینے والی، دماغ کو پراگندہ کرنے والی اور سینے میں حشر بپا کرنے والی کیفیتوں کے بے کم وکاست بیان کا نام نہیں ہے۔ انہیں ایک تخلیقی تجربے میں منتقل کرنے، انہیں ایک نئی زبان دینے کا نام ہے۔ واردات چاہے جتنی ہولناک اور اعصاب شکن ہو، شاعری یا ادب یا فن کی کوئی بھی شکل، محض اس کی رپورٹنگ تو نہیں ہوتی۔ جوش کی قدرت کلام اور ان کے بیان کی گھن گرج کے باوجود اس طرح کی شاعری کسی مؤثر اور پائدار تخلیقی تجربے، کسی رمز آمیز شعری قدر کی تشکیل سے قاصر رہ جاتی ہے۔
مجموعی طور پر اس طرح کی شاعری کے پس پردہ جس شعریات کا تانا بانا تیار ہوتا ہے، وہ اپنی خارجی سطح سے آگے کسی اور باریک اور بلیغ سطح تک ہمیں نہیں لے جاتی۔ غلام ربانی تاباں کی مرتبہ اینتھولوجی میں فساد کے تجربے کا احاطہ کرنے والی جو نظمیں شامل ہیں ان میں سب سے بہتر نظمیں سردار جعفری اور ساحر لدھیانوی کی ہیں۔ ہر چند کہ اپنے زخموں کی نمائش اور اپنی نیک اندیشی کے برملا اظہار کا جذبہ یہاں بھی بہت نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس دیکھئے،
شریف بہنو
غیورماؤ
یہ کس سے فریاد کر رہی ہو
تم اپنے زخموں کی راکھیاں لے کے کس کی محفل میں جا رہی ہو
تمہارے یہ راہبر نہیں ہیں
تمہارے یہ دادگرنہیں ہیں
یہ کاٹھ کی پتلیاں ہیں جن کو
سیاسی پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے مداری
سفید ریشم کی ڈوریوں پر نچا رہے ہیں
یہ سامراجی بساط ِشطرنج کے پیادے ہیں جن کو شاطر
ہزار چالوں سے شاہ و فرزیں بنا بنا کر چلا رہے ہیں
یہی تو ہیں وہ جنہوں نے قانون کے دہکتے ہوئے قلم سے
وطن کے سینے پہ خون ناحق کی ایک گہری لکیر کھینچی
انہوں نے محفل کے ساز بدلے
انہوں نے سازوں کے راگ بدلے
یہی تو ہیں جو تمہارے اشکوں سے اپنے موتی بنا رہے ہیں
تمہاری عصمت، تمہاری عزت، تمہاری غیرت چرا رہے ہیں
(سردار جعفری، آنسوؤں کے چراغ۔۔۔ ہندوستان کے شرنارتھیوں اور پاکستان کے مہاجرین کے نام)
اس نظم سے شاعر کی سماجی حسیت اور اس کے انسانی سروکار کا ایک خاکہ مرتب ہوا ہے۔ جعفری نے استعاراتی طرز اظہار کو برتنے کی جستجو بھی کی ہے لیکن خطیبانہ لے اور لہجے کی بلند آہنگی نے نظم کے محرک تجربے کی عکاسی کے لئے، ایک معروضی تلازمے کی تلاش کے عمل کو محدود کر دیا ہے۔ اسی طرح ساحر لدھیانوی کی نظم ’آج‘ میں ایک طرح کی رومانی افسردگی اور خود رحمی کے جذبے کی ترجمانی، ان کے غم آلود تجربے کو کسی پر پیچ فکری جہت سے ہم کنار کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔
میں تمہارا مغنی ہوں، نغمہ نہیں ہوں
اور نغمے کی تخلیق کا سازوساماں
آج تم نے جلا کر بھسم کر دیا ہے
اور میں اپنا ٹوٹا ہوا ساز تھامے
سرد لاشوں کے انبار کو تک رہا ہوں
میرے چاروں طرف موت کی وحشتیں ناچتی ہیں
اور انساں کی حیوانیت جاگ اٹھتی ہے
بربریت کے خوں خوار عفریت
اپنے ناپاک جبڑوں کو کھولے
خون پی پی کے غرا رہے ہیں
بچے ماؤں کی گودوں میں سہمے ہوئے ہیں
بہنیں بے حرمتی کے تصورسے لرزاں ہیں، افسردہ ہیں، بھائی مجبور ہیں
ہر طرف شور آہ و بکا ہے
اور میں اس تباہی کے طوفان میں
آگ اور خوں کے ہیجان میں
سرنگوں اور شکستہ مکانوں کے ملبے سے پر راستوں میں
اپنے نغموں کی جھولی پسارے
دربدر پھر رہا ہوں
مجھ کو امن اور تہذیب کی بھیک دو!
میرے گیتوں کی لے، میرے سر، میری نے
میرے مجروح ہونٹوں کو پھر سونپ دو
نالہ وفریاد کا یہ رقت آمیز انداز اجتماعی آشوب پر مبنی واردات کے بیان سے کتنا ہم آہنگ ہے اور سماجی سروکار کے اظہار سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، یہاں اس بحث میں جائے بغیر بھی شاید اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ عالمی ادبیات سے قطع نظر، خود اردو میں تاریخ اور گردوپیش کی عام صورت حال کے سیاق میں شعر کہنے کی روایت، اس سے زیادہ کی طلبگار تھی۔ حالی، اکبر، اقبال حتی کہ جوش اور ان کے جونیئر معاصرین تک کے یہاں (جن میں فیض، مخدوم، جعفری، وامق، ساحر، کیفی، نیاز حیدر، سب شامل ہیں) موضوعاتی شاعری کے وقیع نمونے مل جاتے ہیں۔ اقبال نے اپنے پرجلال فلسفیانہ آہنگ اور اپنے خلاقانہ وفو ر کی مددسے سامنے کے موضوعات پر مبنی شاعری کو جس درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا، اس کے پیش نظر جوش، سردار جعفری اور ساحر کی نظموں سے نقل کی جانے والی یہ چند مثالیں بہت معمولی بلکہ عامیانہ دکھائی دیتی ہیں۔
کیسی اندوہ پرور اور دہشت ناک واردات، یہاں خالی خولی لفاظی اور ایک طرح کے سطحی versification کی نذر ہو گئی، اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دور کے دوسرے شعرا کی نظمیں، ان سے بھی بے اثر و ربے کیف ہیں۔ شاعرانہ بیان Poetic statement پر قدرت کے بغیر، بیان کی شاعری (Poetry of Statement) کسی گہری، بامعنی ہیئت کی دریافت میں بہت مشکل سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ پابلو نرودا، لورکا، ناظم حکمت، مایا کا فسکی کے یہاں روزمرہ زندگی سے ماخوذ موضوعات یا تاریخی واقعات اور واردات کے شاعرانہ محاکمے کی جو حیران کن مثالیں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ۱۹۴۷ء کی تقسیم اور برصغیر ہندوپاک کے مختلف علاقوں میں پھوٹ پڑنے والے فسادات، انسانی وحشت اور بربریت کے واقعات کا احاطہ کرنے والی شاعری کا ایسا کال ناقابل فہم ہے۔
اور اس واقعے سے یہی گمان گزرتا ہے کہ ہر انسانی صورت حال اپنے اظہار وبیان کے لئے شعریات کی ایک خاص سطح اور مزاج کا مطالبہ کرتی ہے۔ ۱۹۴۷ء کے آس پاس رونما ہونے والے شعرا اپنے گردوپیش کی زندگی کے تقاضوں سے بالعموم عہدہ بر آ نہ ہو سکے۔ آزادی کے بعد اس موضوع پر جو نظمیں کہی گئیں، ان میں فیض کی نظم ’صبح آزادی‘ اور مخدوم کی نظم ’چاندتاروں کا بن‘ اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں اور اپنے معاصرین کی عام روش سے مختلف ہیں۔ یہی حال اس عہد کے عام فکشن کا ہے۔ تقسیم اور اس سے ملحق تجربوں پر مبنی جو بھی اچھا فکشن لکھا گیا، اس کا بیشتر حصہ اس واقعے کے برسوں بعد سامنے آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہولناک تجربوں کے ایک پورے سلسلے نے لکھنے والوں سے ان کی تخلیقی بصیرت چھین لی تھی اور وہ کسی فنکارانہ سطح پر سوچنے اور اپنا اظہار کرنے سے قاصر تھے۔ زیادہ تر لکھنے والے ایک سکہ بند فارمولے کے مطابق لکھتے رہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی۔ یہاں میں وزیر آغا کے ایک مضمون ’اردو نظم، تقسیم کے بعد‘ (اشاعت، سوغات، شمارہ ۵) سے یہ اقتباس نقل کرنا چاہتاہوں کہ،
’’ادب کی تاریخ میں کوئی واقعہ یا حادثہ اس وقت ایک مرکزی حیثیت کا حامل قرار پاتا ہے جب ایک طول زمانی بُعد کے بعد اس کے بالواسطہ یا بلاواسطہ اثرات ایک بالکل واضح صورت میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ خودادب کی پرکھ بھی زمانی بُعد کی تابع ہوتی ہے کیونکہ بالعموم ادیب اور اس کے زمانے سے قربت کے باعث ایک نامعلوم سی پاسداری یا تعصب جنم لیتا ہے اور استخراج، نتیجہ کے عمل کو ملوث کر دیتا ہے۔ لیکن بعض واقعا ت اس قدر اہم ہوتے ہیں اوران کا دامن اس قدر پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں قیاس آرائی کا عمل کچھ زیادہ ناقابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تقسیم ہند کا واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے اور اگرچہ اس کے دور رس نتائج کے سلسلے میں تو ابھی وثوق کے ساتھ کچھ کہنا ممکن نہیں، تاہم اس کے باعث اردو ادب کے مزاج میں جو تبدیلیاں نمودار ہوئی ہیں، ان کی اہمیت سے انکار کرنا حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے۔‘‘
یہ حقائق کیا ہیں اور تقسیم کے بعد کی نثرونظم میں کس قسم کی تبدیلیاں نمودار ہوئیں، ان کا نقشہ مرتب کرنا اب مشکل نہیں رہ گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو تقسیم کے واقعے پر اب تقریبا ًساٹھ برس گزر چکے ہیں۔ مشترکہ تہذیبی وراثت اور مشترکہ اسالیب زندگی کے بالمقابل پاکستانی دانشوروں کے ایک حلقے میں اپنی انفرادی شناخت کی جستجو اور اس پر اصرار نے بھی اب ایک بھولی ہوئی روایت کی حیثیت حاصل کرلی ہے۔ پاکستانی ادب اور ثقافت کی انفرادیت کا مسئلہ اس وقت ہماری گفتگو کے دائرے سے باہر ہے، اس لئے فی الحال میں اس سوال سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں اور اس سلسلے میں صرف یہ عر ض کرنا چاہتاہوں کہ سیاسی ماحول اور ہندوستان و پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی اور گرمی کے دوران تو بےشک اس سوال کی لے تیز ہو جاتی ہے، لیکن ادیبوں کی اکثریت نے یہ سوال اب سیاست دانوں اور سماجی علوم کے میدان میں کام کرنے والوں کے سپرد کر دیا ہے۔
اب ہندوستان پاکستا ن کے تخلیقی ادب کی دنیا میں یہ شور تھم چکا ہے۔ تاہم اس حقیقت کی نشاندہی یہاں ضروری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں تقسیم کے ادب پر کچی پکی تاریخی اور صحافیانہ انداز کی کتابوں کا ایک سیلاب سا آیا ہوا ہے اور اس موضوع نے ادبی یا تخلیقی وجوہات سے زیادہ سیاسی اور سماجی اسباب کی بنا پر ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔
تقسیم کے بعد کے ادب پر، جس میں تقسیم کے المیے اور اس سے وابستہ واقعات کی روشنی میں نثر و نظم کی مختلف صنفوں پر نظرڈالی گئی تھی، پہلی معروف کتاب ڈاکٹر اعجاز حسین کی ’اردو ادب آزادی کے بعد‘ ہے۔ لیکن تقسیم کے ادب یا پارٹیشن لٹریچر کی اصطلاح کا چلن اردو اور انگریزی میں پچھلے کئی برسوں سے عام ہوا ہے۔ لیزلی فلیمنگ نے اپنی کتاب Another Lonely Voice (اشاعت ۱۹۷۹ء، یونیورسٹی آف کیلی فورنیا برکلے) میں منٹو کی کہانیوں کو اسی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے Stories (1) Political Stories, (2) Partition Stories (3) Sympathetic Storiesاور (4) Romantic Stories کے ذیلی عنوانات قائم کئے ہیں اور عنوانات کے تحت منٹو کی کچھ کہانیوں کی خانہ بندی کی ہے۔
قطع نظر اس بات کے کہ یہ تقسیم غیر منطقی بلکہ مہمل ہے اورایک ہی کہانی بیک وقت ان تمام عنوانات کے تحت رکھی جا سکتی ہے، لیزلی فلیمنگ نے ’’پارٹیشن اسٹوریز‘‘ کے موضوعات اور مسئلوں کا احاطہ بہت محدود اور سطحی بنیادوں پر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تقسیم کا ادب، سیاسی، معاشرتی، تاریخی، جذباتی، فکری اور سماجیاتی سطح پر بیک وقت متعدد جہتیں رکھتا ہے۔ یہ جتہیں تقسیم کے فوراً بعد لکھے جانے والے ادب سے زیادہ مستحکم اور مرموز طریقے سے اردو نظم ونثر میں ۱۹۶۰ء کے آس پاس یا اس کے بعد آئیں۔ مثال کے طور پر ۱۹۴۷ء کی تقسیم اور فسادات کو موضوع بنانے والے شاعروں میں جگر، جوش، فیض، جذبی، مخدوم، جاں نثار اختر، ساحر، کیفی، وامق، تاباں، مجاز، احمدندیم قاسمی، فکر تونسوی، غرض کہ چھوٹے بڑے تقریبا تمام شاعروں کے نام شامل ہیں، لیکن تقسیم کی شاعری یا Partition Poetry کو اس کا بنیادی تشخص ناصر کاظمی کے واسطے سے ملا۔
ناصر نے اپنے پہلے مجموعے ’برگ نے‘ کے تعارف میں لکھا تھا کہ ’’نالہ محفلیں برہم نہیں کرتا۔ نالہ آفریں پر جو کچھ بھی گزری ہو، اس کی فریاد فن کے سانچے میں ڈھل کر نغمہ نہیں بن سکتی تو محض چیخ پکار ہے۔‘‘ ان کایہ انداز نظر تقسیم کے فوراً بعد کی شاعری اور ناصر کاظمی کے ساتھ منظر عا م پر آنے والی شاعری کے درمیان ایک خط امتیاز قائم کرتا ہے۔ ’برگ نے‘ کی کچھ غزلوں میں جذباتی غلو، اعصابی تشنج اور ہسٹیریائی ردعمل کی ویسی ہی صورتیں دکھائی دیتی ہیں جو ان کے پیش روؤں کی شاعری کو شاعری کے بجائے سیدھی سادی نعرے بازی بنا دیتی ہیں لیکن رفتہ رفتہ ۱۹۴۷ء کی تقسیم، اس کے بعد رونما ہونے والے فسادات، فسادات کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے ہجرت کے تجربے یا بے زمینی کے احساس اور انسانی رشتوں کی شکست وریخت کے تصور نے ناصر کاظمی کی شاعری میں ایک نیا مفہوم پایا۔
بے زمینی، مسافرت، معاشرتی ابتری اور انسانی تعلقات کی بے توقیری نے ایک نئی تخلیقی واردات، ایک نئے تجربے کی شکل اختیار کر لی۔ ناصر کاظمی کے اس بیان سے ان کی تخلیقی موقف کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ’’نالہ آفرینی جبر و اختیار کا ایک انوکھا کرشمہ ہے۔ قاری کے دل میں جگہ پانا بھی محض اس کے بس کی بات نہیں۔‘‘ دیکھنا یہ ہے کہ ایک آواز ہزاروں کی آواز بن بھی سکتی ہے یانہیں۔ اس نکتے کی وضاحت کے لئے میں یہاں ناصر کاظمی کے کچھ شعر نقل کرنا چاہتا ہوں۔
رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ
لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ
اب کی فصل بہار سے پہلے
رنگ تھے گلستاں میں کیا کیا کچھ
کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو!
جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ
دل ترے بعد سو گیا ورنہ
شور تھا اس مکاں میں کیا کیا کچھ
(۱۹۴۷ء)
یہ شب یہ خیال و خواب تیرے
کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے
شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا
باقی ہیں تمام رنگ میرے
آنکھوں میں چھپائے پھررہا ہوں
یادوں کے بجھے ہوئے سویرے
دیتے ہیں سراغ فصل گل کا
شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے
منزل نہ ملی تو قافلوں نے
رستے میں جمالیے ہیں ڈیرے
جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو
بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے
روداد سفر نہ چھیڑ ناصر
پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے
(۱۹۴۸ء)
گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ
دلّی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ
سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بے کار
راتوں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ
سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فن کار
بھور بھئے اب ان گلیوں میں کون سنائے جوگ
جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان
دن ڈھلتے ہی دھیان میں آئے کیسے کیسے لوگ
ناصر ہم کورات ملا تھا تنہا اوراداس
وہی پرانی باتیں اس کی وہی پرانا روگ
(۱۹۴۹ء)
یہ مثالیں تقسیم کے تجربے سے گزرنے کے فوراً بعد کی ہیں اوران میں صورت حال کا بیان بے ساختہ طور پر کیا گیا ہے۔ بتدریج اداسی اور دل گرفتگی کی ایک مستقل صورت ناصر کی شاعری کا شناس نامہ بنتی گئی۔ جیسے جیسے ان میں اور ان کے ماضی میں ایک فاصلہ پیدا ہوتا گیا، ان کے باطنی لینڈ اسکیپ کے رنگ پہلے سے زیادہ روشن ہوتے گئے۔ اس سلسلے میں ناصر کے دوسرے مجموعے ’دیوان‘ (اشاعت ۱۹۷۳ء) کی ایک غزل جس کا مجموعی آہنگ ایک نوحے کا ہے اور ان کی نظموں کی کتاب ’’نشاط خواب‘‘ (اشاعت ۱۹۷۷ء) کی ایک نظم (عنوان، نشاط خواب) کی طرف دھیان جاتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں تقسیم، ہجرت اوراجتماعی ماضی کی بازیافت یا تقسیم کے سیاق میں حافظے کے غم آمیز عمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ غزل کے اشعار جن کے اسلوب اور داخلی آہنگ سے ایک تھکے ہارے سفر کے ساتھ ساتھ ایک موہوم امید کی تصویر ابھرتی ہے، حسب ذیل ہیں،
رہ نوردِ بیابانِ غم، صبر کر صبر کر
کارواں پھر ملیں گے بہم صبر کر صبر کر
بے نشاں ہے سفر، رات ساری پڑی ہے مگر
آ رہی ہے صدا دم بدم صبر کر صبر کر
تیری فریاد گونجے گی دھرتی سے آکاش تک
کوئی دن اور سہہ لے ستم صبر کر صبر کر
تیرے قدموں سے جاگیں گے اجڑے دلوں کے ختن
پا شکستہ غزال حرم صبر کر صبر کر
شہر اجڑے تو کیا ہے کشادہ زمین خدا
اک نیا گھر بنائیں گے ہم صبر کر صبر کر
پہلے کھل جائے دل کا کنول پھر لکھیں گے غزل
کوئی دم اے صریر قلم صبر کر صبر کر
درد کے تار ملنے تو دے ہونٹ ہلنے تو دے
ساری باتیں کریں گے رقم صبر کر صبر کر
دیکھ ناصر زمانے میں کوئی کسی کا نہیں
بھول جا اس کے قول و قسم صبر کر صبر کر
اور ناصر کی نظم ’نشاط خواب‘ تو شاید آزادی اور تقسیم کے بعد لکھا جانے والا سب سے خوبصورت اور ایک نجی واردات کے بیان کے باوجود عام اجتماعی خسارے کا احساس پیدا کرنے والا ’’شہرآشوب‘‘ ہے۔ اس حزنیہ قصیدے کا اختتام مندرجہ ذیل شعروں پر ہوتا ہے،
دل کھینچتی ہے منزل ِآبائے رفتنی
جو اس پہ مرمٹے وہی قسمت کے تھے دھنی
وہ شہر سو رہے ہیں جہاں کاظمین کے
ہیبت سے جن کے گرد ہوئے کوہِ آہنی
انبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے
میں ہوں اس لٹے ہوئے قریے کی روشنی
اے ساکنان ِخطہ لاہور! دیکھنا
لایاہوں اس خرابے سے میں لعل معدنی
جلتا ہوں داغِ بے وطنی سے مگر کبھی
روشن کرے گی نام مرا سوختہ تنی
خوش رہنے کے ہزار بہانے ہیں دہر میں
میرے خمیر میں ہے مگر غم کی چاشنی
یا رب زمانہ ممتحن اہل صبر ہے
دے اس دنی کو اور بھی توفیق دشمنی
ناصر یہ شعر کیوں نہ ہوں موتی سے آبدار
اس فن میں کی ہے میں نے بہت دیر جاں کنی
ہر لفظ ایک شخص ہے، ہر مصرع آدمی
دیکھو مری غزل میں مرے دل کی روشنی
تقسیم کے بعد پیش آنے والے واقعات، اس دور کی عام فضا اور ذہنی وجذباتی ماحول اور ایک ملک کے دو ملکوں میں بانٹ دیے جانے کے مجموعی تجربے کی روشنی میں دیکھا جائے تو ناصر کاظمی کی شاعری ایک فرد کی آواز سے زیادہ ایک طرز احساس اور سوچنے کے ایک اسلوب کی ترجمان دکھائی دیتی ہے۔ یہ اسلوب فکر پاکستانی قوم اور سیاست دانوں کے سرکاری زاویہ نظر official view کے بجائے ایک سیدھے سچے ذاتی رویے personal view کی شہادت دیتا ہے۔ اسی حقیقت کا اطلاق ہماری اجتماعی تاریخ کے اس خاص موڑ پر حیران، پریشان اور سراسیمہ دکھائی دینے والے زیادہ تر ادیبوں کی تخلیقات پر کیا جا سکتا ہے۔ ’ آگ کا دریا‘ (اشاعت ۱۹۵۹ء) جسے تقسیم کے بعد منظر عام پر آنے والے پہلے اہم ناول کی حیثیت حاصل ہے اور جسے ہم فریڈرک جیمسن کی وضع کردہ اصطلاح کے مطابق ایک قومی تمثیل یا national allegory سے تعبیر کر سکتے ہیں، اسے تقسیم کے ادب میں ایک نمائندہ ترین تخلیقی دستاویز قرار دیا جا سکتا ہے۔
اس زاویہ نظر کی سچائی سے انکار کرنے والے یہاں نسیم حجازی یا ایم اسلم کا نام لے سکتے ہیں جن کے ناول (بالترتیب ’خاک اور خون‘، ’رقص ابلیس‘ ) پاکستانی حکومت کے official view سے پوری طرح ہم آہنگ تھے اور دو قومی نظریے کی منطق کے مطابق لکھے گئے تھے۔ ایسے کچھ اور ناول بھی منظرعام پر آئے مثلاً رامانند ساگر کا، ’اور انسان مر گیا۔‘، رشید اختر ندوی کا ناول ’۱۵ اگست‘، رئیس احمد جعفری کا ناول ’مجاہد‘ اور قیسی رام پوری کے ناول ’خون‘، ’ بے آبرو‘ اور ’فردوس۔‘ لیکن ان میں سے بیشتر میں جذباتیت کا گراف بہت اونچا ہے اور انہیں سنجیدہ ادب کے دائر ے میں نہیں رکھا جا سکتا۔
اجتماعی دیوانگی اور تشدد کی اس فضا میں، جو فسادات، غارت گری، فرقہ پرستی کی بو سے بوجھل تھی اور ہمارے ماضی کی مشترکہ قدروں سے الگ ایک منصوبہ بند علاحدگی پسندی کی ترجمان تھی، اسے ایک محدود لیکن حقیقت پر مبنی متوازی میلان کے طور پر دیکھا جانا چاہئے۔ اس میلان کو ایک طرح کی عارضی قبولیت ان حلقوں میں بھی ملی جن کا خمیر تو ہند اسلامی تہذیبی روایت کا پروردہ تھا لیکن جن کے لئے اپنے گھر کے اجڑنے کا، اپنے بے وطن ہونے اور بےزمینی کی اذیت سے دوچار ہونے کاغم اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے نسلی حافظے کے دائرے کو توڑ تاڑ کر وقتی طور پر باہر نکل آئے تھے۔ حال کے دباؤ نے ان سے اجتماعی ماضی کا احساس چھین لیا تھا۔ ان کے پیچھے اب صرف معاشرتی زندگی کے انتشار اور دہشت کی کہانیاں تھیں اور سامنے ایک غیریقینی موہوم مستقبل کی سیال تصویر۔
ایسا لگتاہے کہ انہیں حالات کے اس اچانک موڑ پر، تاریخ کی اس غیر متوقع کروٹ پر کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سامنے کی حقیقتوں نے جس طرح بہا دیا، بے مرضی اور بے ارادہ بس اسی طرح بہہ گئے۔ ہجرت کے تجربے سے گزرنے والے ادیبوں کی اکثریت کا، اس وقت یہی حال تھا۔ پاکستانی ادب کے علاحدہ تشخص اور اسلامی ادب کی تخلیق و تعمیر کے نعرے اسی ماحول میں بلند ہوئے۔ مگر ان کا انجام سب کو معلوم ہے! یہ گرد بالآخر چھٹ گئی اور یہ جوش کچھ ہی دنوں میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ جس تحریک کو اچھے لکھنے والے نہ مل سکیں اس کا حشر یہی ہونا تھا۔
اس پس منظر میں، ترقی پسند شاعروں اور افسانہ نگاروں کی عام فکر، نیز تقسیم، فسادات اور ابتری کا شکار ہونے والی زندگی اوراس زندگی کی اخلاقی اساس کے بارے میں ان کے عام انداز نظر کا جائزہ لیا جائے تو ایک حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ اس کی نشاندہی ضرور ی ہے۔ ظاہر ہے کہ ۱۹۴۷ء کے زمانے کا طوفانی ماحول اور انتہاپسندیوں کا وہ دورعام انسانوں کے ساتھ تخلیقی زندگی گزارنے کے لئے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان میں سے کچھ تو سلامتی کے ساتھ آگ اور خون کے اس دریا کے پار اتر گئے۔ کچھ اس ہولناک حقیقت کے پیچ میں الجھ کر رہ گئے۔
رامانند ساگر کا ناول ’اور انسان مر گیا‘، خواجہ احمد عباس کی نیم صحافتی انداز کی کہانیاں جو فسادات کے موضوع پر لکھی گئیں، کرشن چند کے متعدد افسانے، عصمت چغتائی کا ڈرامہ’دھانی بانکیں‘، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور اور شکیلہ اختر کی کئی تخلیقات، یہ سب کے سب ایک گہرے رومانی درد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن کہانی صرف نیک اندیشوں سے اور صحت مندجذبوں سے نہیں بنتی۔ آدرش واد اور پروپیگنڈے کا عنصر ان میں بہت نمایاں ہے۔ ممتازشیریں کا خیال ہے کہ،
’’بہت سے ادیب خود اس طوفان کی زدمیں آگئے تھے اور کئی ایک ذہنوں کو اس ٹریجڈی کی ہولناکی نے ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ وہ کچھ لکھنا چاہتے تھے، ان کے پاس مواد بھی تھا لیکن سنبھل کر لکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ٹریجڈی اتنی بڑی ہی نہیں، اپنی نوعیت میں ایسی ہولناک تھی کہ کسی کو سوجھ نہیں رہا تھا کہ اسے کیسے پیش کریں۔۔۔ حد سے زیادہ احتیاط اور شعور کی کوشش نے ان افسانوں کوبے روح اور بے اثر بنا دیا۔‘‘
شاعری ہو یا فکشن نگاری، موضوعاتی حدبندیاں انہیں اکثر راس نہیں آتیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر لکھنے والے کی فکر بھی منصوبہ بندی اور پہلے سے طے شدہ نتائج کے ساتھ اپنے اظہار پر مصر ہو تو معاملہ مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ پریم چند نے اپنے عہد کے نئے لکھنے والوں کو حسن کا معیار بدلنے کا مشورہ دیا تھا، حسن اور تناسب کے احساس سے غفلت اور بےنیازی کا نہیں۔ تقسیم اور فسادات کے خوں چکاں ماحول میں بہت سے لکھنے والے، ادب اور غیرادب میں فرق کرنا بھول گئے تھے۔ انسانی قدروں کی پامالی اور ہر بڑے یقین اور اعتماد کی شکست کے اس دور میں سلیقے کے ساتھ لکھنے کے آداب سے قطع نظر، گہرائی کے ساتھ سوچنے کے آداب کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس قسم کی نفسیاتی فضا میں اپنے آپ سے الجھتے رہنا یا اپنے آپ کو جذباتی انتہاپسندی کے راستے پر ڈال دینا، شاید زیادہ آسان تھا۔ شاید بڑی حد تک فطری بھی تھا۔ بہت سے شاعر اور فکشن نگار تذبذب کے ایسے شکار ہوئے کہ سمتوں کا احساس کھو بیٹھے۔ اپنی ہی بات سے اچانک پلٹ جاتے تھے اور بعض اوقات اپنے عام موقف سے یکسر متضاد موقف اختیار کرنے لگتے تھے۔
غرض کہ عجیب طرح کی فکری افراتفری کا عالم تھا۔ نفسیاتی کشمکش اور گومگو کی جس کیفیت کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، اس کیفیت سے ناصر کاظمی کے کلام سے ایسی مثالیں بھی ڈھونڈ نکالی جا سکتی ہیں جن سے تقسیم اور ہجرت کے تجربے کی طرف ان کے غالب رویے کی تردید ہوتی ہے۔ فتح محمد ملک نے تومنٹو تک کے یہاں ایسے بیانات کا سراغ لگایا ہے جو دو قومی نظریے کی وکالت کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعدایک طرف تو منٹو کے یہ الفاظ ہیں کہ،
’’سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان اپنا وطن ہے یا پاکستان، اور وہ لہو کس کا ہے جو ہر روز اتنی بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، وہ ہڈیاں کہاں جلائی یا دفن کی جائیں گی جن پر سے مذہب کا گوشت پوست چیلیں اور گدھ نوچ نوچ کر کھاگئے تھے۔ ہندو اور مسلمان دھڑا دھڑ مر رہے تھے، کیسے مر رہے تھے، کیوں مر رہے تھے؟ ان سوالوں کے مختلف جواب تھے۔ بھارتی جواب، پاکستانی جواب، انگریزی جواب۔ ہر سوال کا جواب موجود تھا مگر اس جواب میں حقیقت تلاش کرنے کا سوال پیدا ہوتا تو اس کا کوئی جواب نہ ملتا۔ کوئی کہتا اسے غدر کے کھنڈرات میں تلاش کرو۔ کوئی کہتا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت میں ملےگا۔ کوئی اور پیچھے ہٹ کر اسے مغلیہ خاندان کی تاریخ میں ٹٹولنے کے لیے کہتا۔ سب پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جاتے تھے اور قاتل اور سفاک برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔‘‘ (بہ حوالہ ڈاکٹر برج پریم، منٹو کتھا، ص ۷۳)
دوسری طرف فتح محمد ملک کی کتاب ’سعادت حسن منٹو، ایک نئی تعبیر‘ کے ایک مضمون ’منٹو کی پاکستانیت‘ کا یہ اقتباس ہے کہ،
’’سعادت حسن منٹو نے خود کو اگست سن سینتالیس میں پہچانا۔ وہ ہمارے تخلیقی لکھنے والوں کی اس نسل کے ممتاز ترین فن کاروں میں سے ایک ہیں جوبیسویں صدی کی تیسری دہائی میں اردو ادب کے افق پر نمودار ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی حد بندیوں سے ماورا اور قومی تقاضوں سے ناآشنا ہونے کو اپنے لیے باعث فخر گردانتے تھے اور یوں اپنی ہندو یا مسلمان شناخت کو مٹاکر انسانیت کے اونچے سنگھاسن پر براجمان ہو جانے کوترقی پسندی یا جدیدیت کا لازمہ قرار دیتے تھے۔ ان کا ادبی مزاج مغربی اشتراکیت یا مغربی جدیدیت کے زیر اثر پختگی کو پہنچا تھا۔‘‘
اور یہ کہ، ’’سعادت حسن منٹو بھی اپنے معاصرین کی طرح سیکولر انداز نظر کو وسیع النظری، انسان دوستی اور آفاقیت کی ماں تصور کرتے تھے۔ اس لئے مسلمان قوم کی اس تہذیبی یا سیاسی جدوجہد سے بھی وہ سراسر لاتعلق رہے، جسے تحریک پاکستان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے نظریہ اور عمل سے یہی ثابت کرنے میں کوشاں رہے کہ برصغیر میں جداگانہ مسلمان قومیت کی بنیاد پر ایک علیحدہ مسلمان مملکت کے قیام کا مطالبہ رجعت پسندانہ مطالبہ ہے۔ منٹو تحریک پاکستان سے اس حد تک لاتعلق تھے کہ جب پاکستان قائم ہو گیا، فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑک اٹھی اور منٹو کے ہندو دوستوں تک نے اس کی انسانی پہچان کو فراموش کرکے اس کی مسلمان شناخت پراصرار کیا، تب اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ وہ خود توبے شک دین وملت اور تہذیب و معاشرت کے چھوٹے بڑے اختلافات کو خاطر میں نہ لانے والا انسان ہوا کرے، مگر بحران کی ہر گھڑی میں اس کا مقدر مسلمان قوم ہی سے وابستہ رہےگا۔ وہ اپنے اس مقدر سے نہ تو سیکولرزم کے نام پر نجات پا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آفاقی طرز فکر کی بنیاد پر۔ جہاں فسادات میں مسلمان قتل کیے جارہے ہوں گے، وہاں قاتل کا خنجر اسے بھی واجب القتل ٹھہرائےگا۔۔۔‘‘
۱۹۴۷ء کی تقسیم اور اس سے مربوط واقعات، انسانی سطح پر ایک انتہائی مشکل اور پر پیچ صورت حال کا پتہ دیتے ہیں۔ اس صورت حال میں بہتو ں کے لیے ذہنی اور جذباتی توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ فرقہ وارانہ جنون اور بہیمانہ تشدد کی اس فضا میں بہت سے اعتبار ٹوٹے اور کئی ایسے لکھنے والوں کا یقین بھی متزلزل ہوا جو ۱۹۴۷ء کے آسیب سے نکلنے کے بعد اب اس پوری واردات کو ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں اور جو مشترکہ تہذیبی وراثت اور اقدار کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انتظار حسین، جن کی پوری تخلیقی زندگی اپنا ایک خاص تشخص رکھتی ہے اور جس تشخص کی تعمیر روشن خیالی، رواداری اور انسان دوستی کے گہرے تصورات کی بنیاد پر ہو ئی ہے، ۱۹۴۷ء کے فوراً بعد کے دور میں ایک الگ نہج پر سوچ رہے تھے۔
تقسیم کی واردات، ان کے لیے بھی جذباتی انتہاپسندی کا اور تہذیبی ہم آہنگی میں یقین کی شکست کا سندیسہ لے کر آئی، اس وقت ان کی سوچ، ان کے موجودہ فکری میلانات اور تخلیقی موقف سے مسلسل برسرپیکار تھی۔ اب تو شاید انہیں خود اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین کرنے اور اپنے اس وقت کے زاویہ نظر کو جو جذباتی ابال اور ایک اندوہناک اشتعال کے ماحول میں مرتب ہوا، قبول کرنے میں تامل ہوگا، لیکن ۱۹۴۷ء کے بعد انہوں نے بہت پرجوش اندازمیں یہ سب لکھا تھا کہ، ’’۔۔۔ فسادات کے افسانوں کے بارے میں پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ فسادات کے افسانے ہیں یا نہیں۔۔۔ آگ اور خون کا یہ ہنگامہ جو گرم ہوا تھا وہ خلا میں نہیں اگا تھا۔ اس کا ایک آگا پیچھا تھا اور اس آگا پیچھا کے سلسلے میں صرف یہ کہہ کر پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا کہ یہ سب انگریزی سامراج کی کارستانی تھی۔۔۔ تو یوں سمجھیے کہ جس چیز کو ہم فسادات کہتے ہیں وہ ایک پیچیدہ قومی واقعہ ہے جس کے مختلف خارجی اور داخلی پہلو ہیں۔‘‘
’’ان افسانوں کا ایک پروپیگنڈائی پہلو بھی ہے جس کی بنا پر وہ سیاسی نقطہ نظر سے بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ پس اگر قومی نقطہ نظر کے تحت میں ادبی لحاظ سے کم تر درجے کے افسانوں پر بھی سنجیدگی سے بحث کروں تو شاید قابل اعتراض بات نہ ہوگی۔‘‘
’’مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کی سیاسی جدوجہد میں ان کے ادیب ان سے ٹوٹ گئے۔ ملت کی سیاسی جدوجہد سے وابستگی کی روایت اقبال پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کانگریس کا پروپیگنڈہ یہ رنگ لایا کہ اس قسم کی وابستگی فرقہ پرستی شمار کی جانے لگی۔‘‘
’’اردو افسانے میں متحدہ قومیت کے نظریے کی موت پرٹسوے بہائے گئے۔ برطانوی سامراج کو گالی کوسنے دیے گئے اور اس برعظیم کے پھر ایک ملک ہو جانے کے خواب دیکھے گئے۔ کرشن چندر نے افسانہ پڑھنے والوں اور افسانہ لکھنے والوں، دونوں کو گہرے طور پر متاثر کیا ہے اور کرشن چندر اس نظریے کا سب سے بڑا مبلغ ہے۔ بات سیدھی سادی تبلیغ پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ’ہم وحشی ہیں‘ کی اشاعت سے اردو ادب میں فرقہ پرستی کی باقاعدہ ابتدا ہوتی ہے۔
سانحہ دراصل یہ ہے کہ بعض بہت ہی سنجیدہ قسم کے افسانہ نگار اس غیر سنجیدہ روش کے شکار ہوگئے۔ مجھے سب سے زیادہ غم عصمت چغتائی کی موت کاہے۔ جہاں ’دھانی بانکیں‘ کا تعلق ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال اب بھی جوں کا توں موجود ہے کہ آیا یہ ڈرامہ عصمت کا لکھا ہوا ہے یا نہیں۔‘‘
’’اگر قومی ضرورت یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں تو ادیب کو یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ پمفلٹ بازی واقعی بڑی مکروہ چیز ہے۔ عام حالات میں توا س کے نام ہی سے ادیب کو ابکائی آ جانی چاہئے لیکن دقت یہ ہے کہ آج کے ہمارے حالات عام حالات نہیں ہیں۔ افراد کو ہی نہیں بلکہ قوموں کو زندہ رہنے کے لئے بہت سے اچھے برے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ قوم زندہ رہنا چاہتی ہے اور اپنی گذشتہ ناکامیوں کے داغوں کو دھونا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ پروپیگنڈائی ادب کی محتاج ہے اور پاکستانی ادیب اگر پاکستانی ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتا تو اسے پمفلٹ بازی پر اترنا پڑےگا۔‘‘ (ساقی، کراچی، جون ۱۹۴۹ء، بحوالہ ظلمت نیم روز، مرتبہ، ممتاز شیریں)
یہ ایک طرح کی عارضی بدحواسی اور تاریخ کے جبر کا نتیجہ ہے۔ نطشے نے کہا تھا کہ تاریخ کبھی کبھی ہمارے راستے کا پتھربن جاتی ہے اور کوئی بڑا تخلیقی کارنامہ انجام دینے کے لئے بعض اوقات تاریخ کو بھولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تقسیم کے پس منظر کی بھی ایک اپنی تاریخ تھی، بہت الجھی ہوئی۔ جذبہ انگیز اور احساسات کو بوجھل کر دینے والی تاریخ۔ اس تاریخ کا سب سے الم ناک اور آزمائشی پہلو اسے عقبی پردہ مہیا کرنے والی فرقہ وارانہ سیاست تھی۔ اس میں الجھنے کا مطلب تھا اپنے شعور کو علاحدگی پسندی کی اس سیاست کے حوالے کر دینا۔ ظاہر ہے کہ اردو نظم ونثر کی کا وہ حصہ جو ایک دوسرے سے برسرپیکار دو قوموں کے انفرادی تشخص پر اصرار کرتا ہے، علاحدگی پسندی کی اسی سیاست کا نمائندہ ہے۔
اس قسم کی تحریریں بالعموم لکھنے کی جلدی میں لکھی گئیں۔ اس لئے ان کا اندازہ تخلیقی سے زیادہ صحافیانہ ہے۔ ممتازشیریں نے تقسیم، فسادات اور اردو افسانے کے باہمی رشتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک معنی خیز بات یہ کہی تھی کہ ’’فسادات اس وقت تک کسی پائیدار ذہنی تجربے کی حد میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعضے لکھنے والوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ اس فضا میں کس قسم کے افسانے لکھے جانے چاہئیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنی اپنی حد مقرر کر لی تھی اور اپنی جذباتی مجبوریوں کے تحت خود کو اس تخلیقی آزادی سے اپنے آپ ہی محروم کر لیا تھا، جو کسی فن پارے کو نامعلوم نتائج تک پہنچانے میں معاون ہوتی ہے۔‘‘ لہذا تقسیم اور فسادات کے زیر اثر جو منصوبہ بند فکشن وجود میں آیا، اس کی شکل کچھ اس طرح کی تھی،
(۱) جہاں تک ممکن ہوا فسانوں میں ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کو برابر کا قصوروار بتایا جائے۔
(۲) غیر جانب داری کا تاثر برقرار رکھا جائے۔
(۳) اختتام اس نکتے پر ہوا کہ بالآخر اسی ابتری اور انتشار کی تہہ سے ایک نئے انسان کا ظہور ہوگا اور انسانیت کی بحالی ہوگی۔
برصغیر کا سماجی اور ذہنی لینڈ اسکیپ اس وقت بڑی حد تک پہلی جنگ عظیم کے بعد کے یورپ سے مماثل تھا، جہاں کسی مرکزی اقتدار کی عدم موجودگی کے باعث اشیا اپنا توازن کھو چکی تھیں۔ ایک دوسرے سے ٹوٹ رہی تھیں اور بکھر رہی تھیں اور تشدد کے اس ماحول میں تخلیقی طرز احساس پر بھی ایک طرح کی دہشت خیزی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جیسا کہ اس گفتگو میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ اضطراب آگیں اور سراسیمگی پیدا کرنے والی فضا کسی تخلیقی تجربے کی تشکیل کے لئے بہت سازگار نہیں تھی۔ اس فضا میں کسی بھی حساس روح کے لئے گردوپیش کے واقعات اور اپنے فن کارانہ موقف کے مابین اس معروضی فاصلے کو قائم رکھنا آسان نہیں تھا، جو اپنے جذبوں کی تنظیم اور ذہنی ردعمل کے تناسب کے لئے ضروری ہے۔
تقسیم کے تجربے پر مبنی تمام قابل ذکر ناول، آگ کا دریا (قرۃ العین حیدر)، اداس نسلیں (عبداللہ حسین)، آنگن (خدیجہ مستور)، بستی (انتظارحسین)، تذکرہ (انتظارحسین)، اسی لئے تقسیم کے برسوں بعد لکھے گئے۔ ۱۹۴۷ء اور ۱۹۵۰ء کے درمیان شائع ہونے ولے ناولوں میں قرۃ العین حیدر کا، ’میرے بھی صنم خانے‘، عزیز احمد کا ’ایسی بلندی ایسی پستی‘ اور محمد احسن فاروقی کا ’شام اودھ‘ ایک غیر منقسم معاشرے اور تہذیبی منظرنامے کو اپنا موضوع بناتے ہیں لیکن ان میں زیادہ زور مخلوط اسالیب زندگی اور قدروں پر ملتا ہے، فسادات پر نہیں۔
ڈاکٹر روزی سنگھ کی کتاب Rilke, Kafka, Manto، The semiotics of love Life and Death کے تعارف میں پروفیسر ہرجیت سنگھ گل (پروفیسر ایمریٹس، جواہر لال یونیورسٹی) نے فسادات کے موضوع پر منٹو کی کہانیو ں کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ’’منٹو کے لئے مذہبی اور سماجی ثقافتی ماحول کا حوالہ بے معنی ہے۔ وہ حساسیت اور انسانی وقار کے نشان، معاشرے کے سب سے حقیر کرداروں کی ہستی میں بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور اگرچہ اس کے کرداروں کاردعمل اور برتاؤ، ہمیں قدرے مبالغہ آمیز دکھائی دیتا ہے اور ایک طرح کی ماورائے حقیقت کی سطح تک جا پہنچتا ہے، لیکن منٹو کے تخلیقی متون ہمیشہ غیر معمولی اور بےمثال انسانی ڈسکورس بنے رہتے ہیں۔‘‘
افسوس کہ اردو میں تقسیم کے ادب کا بہت کم حصہ اس زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ۱۹۴۷ء کی واردات بہت بڑی تھی۔ اسے اپنی تخلیقی جستجو اور سرگرمی کے طور پر برتنے والے اتنے بڑے نہیں تھے۔ یا یوں کہا جائے کہ اس وارادت کے تقاضے، لکھنے والوں سے بہت سخت تھے۔ چنانچہ گنتی کے چند افسانے، نظمیں، غزلیں اور ناول اس عظیم الشان موضوع کے مطالبات ادا کر سکتے ہیں۔ نظم اور نثر میں کسی بھی بیانیے کی تعمیر کرنے والا اپنی تحریر کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کے باہر بھی۔ وہ اپنے بہت سے شخصی، معاشرتی اور تہذیبی مرحلوں کو عبور کرنے کے بعد اپنے تخلیقی منطقے تک پہنچتا ہے۔ اسی لئے کسی خاص صورت حال کے تئیں ہر بڑے لکھنے والے کا رویہ اور جوابی ردعمل اس کی نجی ملکیت ہوتا ہے۔ تقسیم کے ادب کے سیاق میں بیدی، منٹو، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، انتظار حسین اور ناصر کاظمی نے جو مستقل حوالوں کی حیثیت اختیار کی تو اسی لئے کہ ان کی نگارشات اپنے دور کی عامیانہ فکر اور طرز احساس سے الگ ایک شخصی اور وجودی سطح پر اپنے موضوع سے رشتہ قائم کرتی ہیں۔
ممتاز شیریں نے تقسیم کے ادب پر اپنی اینتھولوجی میں کل سترہ کہانیاں شامل کی ہیں۔ قرۃالعین حیدر (لیکن آشیانہ جل گیا)، عزیز احمد (کالی رات)، کرشن چندر (پشاور ایکسپریس)، حیات اللہ انصاری (شکر گزار آنکھیں)، منٹو (ٹھنڈا گوشت اور کھول دو)، رامانند ساگر (بھاگ ان بردہ فروشوں سے)، پریم ناتھ در (آخ تھو)، سہیل عظیم آبادی (اندھیارے میں ایک کرن)، اوپندر ناتھ اشک (ٹیبل لینڈ)، قدرت اللہ شہاب (یاخدا)، احمد ندیم قاسمی (پرمیشر سنگھ)، اشفاق احمد (گڈریا)، جمیلہ ہاشمی (بن باس)، راجندر سنگھ بیدی (لاجونتی)، عصمت چغتائی (جڑیں) اور انتظارحسین (بن لکھی رزمیہ) ان میں منٹو کی دونوں کہانیوں کو عالم گیر شہرت ملی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کہانیاں تقسیم کے فوراً بعد لکھی گئیں۔ دونوں کہانیوں پر مقدمے چلے اور ان کے حوالے سے تقسیم کے ادب پر بحثوں کے کئی دروازے کھلے۔
یہ کہانیاں بنیادی طور پر اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ تقسیم کے واقعے نے انسان کی جذباتی اور تہذیبی زندگی میں کیسی ہولناک اتھل پتھل پیدا کر دی تھی اور انسانی فطرت کے کیسے کیسے سنگین مظاہر، وجودی شخصیت کے کیسے کیسے مخفی گوشے اس تاریخی وارادت کے واسطے سے سامنے آئے تھے۔ اسی طرح منٹو کے ’سیاہ حاشیے‘ بہ ظاہر عام زندگی سے اپنا مواد اخذ کرتے ہیں لیکن منٹو انہیں اس طرح سامنے لاتا ہے کہ سوئی ہوئی حیرتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ منٹو کا زہرخند ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتاہے اور اس کا قہقہہ سن کر ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ بہ قول عصمت چغتائی، ’’ان لطیفوں کو پڑھ کر رونا آ جاتا ہے۔‘‘ دہشت اور بدہیئتی کی فضا میں یہ ہماری جذباتی تنظیم اور تخلیقی اظہار کے ایک نئے اسلوب کی دریافت تھی۔
’سیاہ حاشیے‘ نے مزاح اور سنجیدگی کے فرق کو مٹا دیا اور یہ اردو فکشن کی روایت میں ایک نئی شعریات کی تشکیل کا تجربہ تھا۔ عام انسانوں کے لئے یہ اجتماعی دہشت اور برہمی کا دور تھا۔ سیاست دانوں کے لیے اپنی اپنی مجروح انا کی کشمکش کا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہماری اجتماعی زندگی سرے سے بے سری ہو گئی تھی اور جذباتی اشتعال کے پرشور ماحول میں زندگی فطرت کے کسی اصول، کسی قدر، کسی روایت، کسی ضابطے اور قانون کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔ مشترکہ وراثت، انسانی رشتوں کا نظام، قومی آزادی کی حصولیابی کے ساتھ رونما ہونے والی روشنی کی کرن، ان میں سے کسی کا احساس باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت صبح آزادی کے ساتھ پھیلنے والا اجالا داغ دار تھا اور دونوں ملکوں کے لئے آزادی ایک بری خبر۔ ہم سب آپ اپنے لیے اجنبی بن گئے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کا رپورتاژ ’دلی کی بپتا‘ صرف ایک شہر کی بربادی کا بیان نہیں ہے، ہمارے پورے اجتماعی ماضی کی بربادی کا بیان ہے۔
ایسی صورت میں واقعات اور حقیقی صورت حال کے دائرے سے خود کو باہر نکال کر اس سب پر نظر ڈالنا تقریباً ناممکن تھا۔ ساری واردات ایک خاص زمان ومکاں میں الجھی ہوئی تھی اور اس کی سطح سے اوپر اٹھ کر خود کو یا دوسرے انسانوں کو ایک تخلیقی تجربے کے طور پر دیکھنا ایک بہت بڑی ذہنی اور فن کارانہ تلاش کی ذمہ داری کو نبھانا تھا۔ فوکو یاما کا تاریخ کے خاتمے (End of History) کا اعلان تو اس واقعے کے تقریباً پچاس سال بعد (۱۹۹۵ء میں) سامنے آیا لیکن ہندوستان اور پاکستان کے لئے ۱۹۴۷ء بربریت کے ایک نئے دور کے آغاز اور اجتماعی تاریخ کے ایک طویل دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ لیکن ادب کی تخلیق کا مقصد، بہرحال سخت ترین آزمائشوں کی فضا میں بھی آفاقی انسانی صداقتوں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حالات چاہے جتنے خراب ہوں، ایک ادبی ڈسکورس بہرحال سماجیاتی، تاریخی، اقتصادی، مذہبی ڈسکورس سے الگ اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔
تخلیقی اور ادبی اظہار اور اسلوب کی گرفت میں آنے کے بعد افراد کسی طبقے یا گروہ میں گم نہیں ہو جاتے۔ ہم اس طرح کی تخلیقات کا مطالعہ تاریخی مواد کے طور پر یا سیاسی اور سماجی دستاویز کے طور پر نہیں کرتے۔ بیدی کی ’لاجونتی‘ یامنٹو کے ’ٹھنڈا گوشت‘، ’کھول دو‘، گور مکھ سنگھ کی وصیت‘، ’یزید‘، ’ٹوبہ ٹیک سنگھ‘ جیسی کہانیوں کامطالعہ ہمارے اجتماعی ماضی یا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ ہولناک تشدد اور دہشت کی تہہ سے نمودار ہونے کے باوجودیہ کہانیاں انسانی تقدیر اور تجربے کی تخلیقی دستاویز کے طور پر سامنے آتی ہیں اور کسی طرح کے سیاسی موقف کی ترجمان نہیں بنتیں۔ یہ انسان، تقسیم اور فسادات کو موضوع تو بناتے ہیں لیکن صرف تقسیم اور فسادات کے ادب کا حصہ نہیں ہیں۔ ان میں کسی طرح کی جذباتیت کا، خودرحمی کا، انفعالیت کا، رقت خیزی کا گزر نہیں۔ شدید ترین جذباتی لمحوں میں بھی فکری ذمہ داری کا احساس قائم رہتا ہے۔ یہی بات انتظار حسین کی معروف کہانی ’بن لکھی رزمیہ‘ پر بھی صادق آتی ہے جسے جدید ہندوستان کے بعض مؤرخوں (مثلا سدھیر چندر) نے ایک آتش فشاں دور کے تخلیقی ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس میں معنی کی کئی جہتیں دریافت کی ہیں۔
اصل میں تشدد، دہشت، اجتماعی دیوانگی اور بہیمیت کے دور کی تخلیقی اور فن کا رانہ تعمیر، یا ذہنی انتشار کی فضا میں کسی منظم تخلیقی اسلوب کی تعمیر، یا اظہار کو کسی پائیدار یا جمالیاتی ذائقے سے ہمکنار کرنے کاعمل، یا ایک دیرپا تاثر قائم کرنے والی شعریات وضع کرنے کی کوشش کے مطالبات سے عہدہ برآ ہونا، غیر معمول تخلیقی ضبط اور فنی رکھ رکھاؤ کے بغیر ممکن نہیں۔ آرول نے کہا تھا کہ جنگ کے دور کا ادب، صحافت ہے، یعنی یہ کہ شعور کی اوپری سطحوں تک محدود اور عجلت پسندی کے ساتھ پیش کیا جانے والا، بڑی حدتک عامیانہ اور بے پیچ یا اسرار کے عنصر سے تہی ردعمل۔
پہلی جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ، جس میں جیمس جوائس کی ’یولیسس‘ اورایلیٹ کی ’ویسٹ لینڈ‘ لکھی گئیں، اس دور کی ویرانی، ابتری اور اندوہ کا بوجھ اٹھانا ہرکس وناکس کے بس کی بات نہ تھی۔ اسپین کی خانہ جنگی کے دور کی عکاسی، جوانسان کی بیچارگی اور بہیمیت کے غرور کی ترجمان کہی جا سکے، اس کے لئے پکاسو کی گوئرنکا کا تخلیقی محاورہ در کا تھا، ایک طرح کا دہشت خیز حسن (terrible beauty) جو روایتی ذوق جمال اور شعریات سے آگے، اظہار کا ایک ایسا اسلوب وضع کر سکے جس میں درشتگی اور جذبے کی سنگینی کا حسن ہو، جس میں کھردراپن ہو۔
جنگیں صرف سپاہی نہیں لڑتے۔ تخلیقی اظہار کا شغل اختیار کرنے والے بھی ان تجربوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنی حسیت کے درد رسیدہ علاقوں سے اپنی توانائی اخذ کرتے ہیں۔ بیدی کی ’لاجونتی‘، منٹو کی ’ٹھنڈا گوشت‘ اور ’کھول دو‘ جیسی کہانیاں رومانی درد کے احسا س سے یکسر خالی ہیں، لیکن انہیں پڑھنے والا ایک پل کے لئے بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کوشش فیض کی زبان میں ایک کڑے درد کو گیت میں ڈھالنے کی ہے۔
ممتاز شیریں نے اپنے یادگار مضمون ’فسادات اور ہمارے افسانے‘ میں ۱۹۴۷ء سے وابستہ عہد کی صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا،
’’فسادات ہمارے لئے بالکل قریبی حقیقت ہیں۔ ہولناک، انتہائی بھیانک، ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی آنکھوں کے سامنے کی حقیقت، یہی وجہ ہے کہ بنے گڑھے پلاٹ اور خالی رقت آفرینی، عبارت آرائی، لفاظی اور طنز کوئی اثر پیدا نہیں کرتے، کیونکہ جن تجربات سے گزرنا پڑا ہے وہ عام ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے گردوپیش کی زندگی میں ہر طرف فسادات کے بھیانک اثرات نظر آتے ہیں۔ فسادات نے زندگی کو تہہ وبالا کر دیا تھا۔۔۔‘‘
’’فسادات کے پیچھے تو اتنا وسیع سیاسی، تاریخی، معاشرتی پس منظر ہے کہ اس پر ٹالسٹائی کے ’جنگ اور امن‘ کی سی چیز لکھی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں کوئی ایسا ادیب نہ ہو جو ایسی چیز لکھے یا لکھ سکے۔‘‘
اس موضوع پر قابل ذکر ناول جو بھی اردو میں لکھے گئے، جیسا کہ اس گفتگو میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے، فسادات اور بہیمیت کا سیلاب تھمنے کے بعد لکھے گئے۔ گنتی کی کچھ اچھی کہانیاں سامنے آئیں جن میں یہاں وہاں کچھ واقعات اور سچوئیشنز (situations) کا بیان غیرمعمولی ہے اور sublime کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ مثال کے طور پر منٹو کے افسانے ’ کھول دو‘ یا عزیز احمد کی ’کالی رات‘ اور حیات اللہ انصاری کی ’شکر گزار آنکھیں‘ کا اختتامیہ یا پھر قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، خدیجہ مستور اور انتظار حسین کے ناولوں کے وہ حصے ہیں جو تقسیم کے تجربے اور لکھنے والوں کی اپنی حسیت کے درمیان ایک معروضی فاصلے کے ساتھ اس وقت لکھے گئے، جب آگ اور خون کا تماشا ختم ہو چکا تھا اور دھوپ سمٹ چکی تھی۔ تشدد، دہشت اور درد کی فضا جب لکھنے والوں کے لئے ایک ڈراؤنے خواب کی یاد بن چکی تھی۔
نوسٹلجیا صرف ایک ذہنی یا نفسیاتی کیفیت ہی نہیں، ایک جمالیاتی ذائقے، ایک تخلیقی طرز احساس کی تلا ش بھی ہے۔ تقسیم کے اد ب کا سب سے نمائندہ اور وقیع حصہ وہی ہے جو ایک پرتشدد ماحول کے بخشے ہوئے تجربے کی بازدید اور اس تجربے کے پیدا کردہ اضطراب کی بازیابی پر مبنی ہے۔ کسی خوں چکاں منظر کی ہیبت اور اذیت کو سمجھنے کے لئے اسے قدرے دور سے دیکھنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں منٹو کی حیثیت استثنائی ہے کہ اس نے تشدد کے تجربے سے زمانی اور مکانی قربت کے باوجود، شاید اپنی تخلیقی سرشت کی سنگینی اور اپنی خداداد صلاحیت کے باعث اپنے آپ کو حالات سے مغلوب نہیں ہونے دیا۔ اپنے آپ کو ہر نوع کی جذباتیت سے، چھچلی رومانیت سے اور رقت خیزی سے بچائے رکھا۔ جس نے ظالم اور مظلوم کے پھیر میں پڑنے کے بجائے، اپنے کرداروں کوصرف انسان کے طور پر دیکھنے اور سمجھنے سے غرض رکھی۔ ’سیاہ حاشیے‘ کی اشاعت کے بعد غالبا اس کے پہلے تفصیلی تبصرے میں ڈاکٹر آفتاب احمد نے لکھا تھا،
’’(منٹو) نے غیرمعمولی حالات میں معمولی باتوں کو نمایاں کرکے زندگی میں ان کی گہری معنویت کا احساس دلایا ہے۔ فسادات کے بارے میں منٹو کو انسان کی بربریت، اس کی مظلومی اور بےبسی نے متاثر نہیں کیا، کیونکہ یہ سب اپنی شدت کے باوجود انسانی روح کی ہنگامی کیفیات ہیں۔ اسے اگر متاثر کیا ہے تو ان بظاہر غیر اہم اور معمولی باتوں نے جو مختلف انسانوں کے شعور میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے خون میں رچی ہوئی اور ہنگامی کیفیات کی شدت کے باوجود بار بار ابھر آتی ہیں۔ کبھی وہ اس کی بلندی کی آئینہ دار ہوتی ہیں اور کبھی اس کی پستی کی، مگر بہر صورت اس کی انسانیت کی۔‘‘
یہ رویہ ہمیں نظیر اکبرآبادی کی نظم ’’آدمی نامہ‘‘ کی یاد دلاتا ہے، جو نظیر کی مخصوص ارضیت اور عنصری سادگی کے ساتھ انسانی وجود کے مختلف زاویوں اور جہتوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ہر بڑے انسانی المیے کی طرح تقسیم اور فسادات کے دور کا تجربہ بھی ایک پرپیچ تجربہ تھا۔ اس کے توسط سے انسانی وجود کے متضاد اور ایک دوسرے سے یکسر مختلف مظاہر سامنے آئے۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ فسادات کے بارے میں لکھنے ولا کیا صرف ایک ادیب کی حیثیت سے لکھ رہا ہوتا ہے؟ ایک شہری کی حیثیت سے اس کا رول اس کے ادبی منصب پر اثرانداز ہوتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان معاشرے میں ایک ساتھ ایک سے زیادہ سطحوں پر زندگی بسر کرتا ہے۔ فسادات کے موضوع پر بہت سی تخلیقات نظم ونثر کی مختلف صنفوں میں، ایسی بھی ہیں جن میں انسانی مقدرات سیاسی اور فرقہ وارانہ تقسیم میں الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور لکھنے والے کا اظہار وعمل، اس کی سرگرمی کے غیر ادبی مسائل سے بار بار متصادم اور مغلوب ہوتا ہے۔
لیکن سیاست، مذہب، معیشت کی طرح ادب اور تخلیقی اظہار کی ایک اپنی لفظیات ہوتی ہے۔ ادب اور آرٹ کی تخلیق کرنے والا اول و آخر اسی لفظیات کا پابند ہے۔ اس کا رول بہرحال ایک سماجی مفکر، ایک سیاست داں، ایک سماجی مصلح کے رول سے الگ ہے۔ اس کے رول کی پہچان اس کے اپنے دائرہ کار اور اس کی تخلیقی ہنرمندی کے واسطے سے ہوگی۔ اسی وجہ سے تقسیم کے ادب اور اجتماعی تشدد کے سیاق میں ہم تک پہنچنے والی بہترین تحریریں وہی ہیں جو لکھنے والے کی ادبی حیثیت سے مشروط ہیں اور ایک ایسی شعریات، ایک ایسے جمالیاتی تجربے، اظہار واسلوب کے ایک ایسے نظام کو اپنا معیار بناتی ہیں جو لکھنے والے کی حیثیت سے اس کا اعتبار قائم کر سکیں۔ ان تحریروں میں انسان کی حیثیت ایک مرکزی کردار کی ہے۔ اس کے باوجود ان میں کسی طرح کا آدرش واد نہیں۔ وعظ وپند کی کوئی کوشش کی، کوئی اخلاق پوز نہیں ہے۔ ان میں فن کارانہ ادراک کی وہ سطح ملتی ہے جہاں نیکی اور بدی دونوں کا شعور ایک ساتھ پڑھنے والے تک پہنچتاہے اور اسے انسانی ہستی کی وحدت، ایک طرح کی گہری اخلاقی مساوات کے احساس تک لے جاتا ہے۔
اسی لئے یہ تخلیقات ہم سے صرف جذبات کی زمین پر مکالمہ قائم نہیں کرتیں، ہمیں انسانی وجود اور ہستی کے اسرار سے بھی متعارف کراتی ہیں اور ہمیں اپنے ماضی اور حال کے علاوہ مستقبل کی بابت سوچنے کا ایک راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ بہ ظاہر عام اور حقیر دکھائی دینے والے کردار، بڑے اور غیر معمولی معاشرتی مسئلوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی طرح صرف تاریخ کے لئے نہیں بلکہ ہماری انسان فہمی کے لئے بھی ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں۔ میں اس معروضے پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ادب تاریخی صورت حال کا بیان نہیں ہوتا بلکہ بجائے خود تاریخ کے پس منظر میں جنم لینے والا ایک قائم بالذات واقعہ ہوتا ہے۔ ہم ۱۹۴۷ء کے تشد د کو بھول جائیں جب بھی اس پرتشدد دور کے سایے سے نکل کر ہم تک پہنچنے والے یہ ادب پارے، ہمارے حافظے پر دستک دیتے رہیں گے۔ تقسیم کے ادب کا نمائندہ حصہ وہی ہے جو ہمارے اجتماعی ماضی کی ایک واردات کو حال سے اور حال کو استقبال سے ملاتا ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ،
آج بھی بزم میں ہیں رفتہ و آئندہ کے لوگ
ہر زمانے میں ہیں موجود زمانے سارے