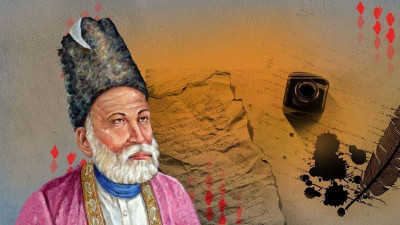تہذیب اور تنقید کا رشتہ
ہمارا دور انسانی تہذیب کی تاریخ کا شاید پہلا دور ہے جب ایک ساتھ بہت سے لوگ ادب کی موت کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ اب لوگوں کے پاس ادب پڑھنے کا وقت نہیں۔ اور وہ لوگ جو اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہونے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں یعنی کہ سیاست داں اور سرمایہ دار، انہیں ادب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عام انسانوں کے لئے زندگی بہت سخت ہے اور جینے کی جدوجہد میں اپنے آپ کو اس طرح صرف کرتے رہتے ہیں کہ تہذیب کے مختلف مظاہر موسیقی، مصوری، رقص، فن تعمیر، کسی پر ان کی نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ چہ جائے کہ ادب۔
ادب تخلیق کرنے والے مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک حلقہ ان کم نصیبوں کا ہے جو ادب تخلیق کرنے کے سوا کچھ اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لئے لکھنا ایک داخلی تقاضے کی تکمیل ہی نہیں، سانس لیتے رہنے کے برابر ہے۔ ایک حلقہ کار مباش کچھ کیا کر، کے مصداق شعر افسانہ لکھتا ہے اور ادب کی تخلیق کو ایک شوق فضول کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ ایک تیسرا حلقہ ان دانش مندوں کا ہے جو ادب کو کیرئیر کے طور پر برتتے ہیں۔ اسے امیروں وزیروں سے لے کر ادب کے طالب علموں تک رسائی کا بہانہ بناتے ہیں۔ انعام پاتے ہیں۔ خوش حیثیتی کا لطف اٹھاتے ہیں، اور ادب کے نام پر نمائشی جذبوں، مستعار تجربوں، اپنی ہستی کی بنیادوں سے کوئی تعلق نہ رکھنے والے تصورات اور آپ اپنی بے یقینی کی فضا میں سانس لینے والے احساسات کی دوکانیں سجاتے ہیں۔
تنقید اپنی مصلحتوں، مجبوریوں، منافقتوں اور اوڑھی ہوئی عادتوں کے مطابق تمام قبیلوں میں چھوٹی بڑی سندیں تقسیم کرتی رہتی ہے۔ ادب لکھنے والا نقاد سے مرعوب کہ اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے۔ پھر نقاد ہی غریب وہ سب کچھ پڑھتا ہے، صرف لکھنے اور پڑھنے والے کو جس کی ہوا تک نہیں لگتی اور اس طرح محض تنقید لکھنے کی خاطر خاصی اذیت ناک زندگی گزارتا ہے۔ نقاد اپنی جگہ خوش ہے کہ اسے اپنی جانکاہی کا صلہ شہرت اور مرتبت، اکرام اور عزت کے طور پر مل جاتا ہے۔ اس کی خوشی کا دوسرا بہانہ یہ ہے کہ بے جان، سوکھی نیرس علمی کتابیں پڑھنا اس کے لئے آج کی تہذیب کے عذاب آمیز سوالوں اور ان کی تاریخ کے اندوہ ناک تجربوں سے گزرنے کی بہ نسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ سو، اس نے مختلف علوم کی کتابوں میں، تجربہ گاہوں میں، ایک محفوظ زندگی کے حصاروں میں خود کو سمیٹ رکھا ہے۔
تہذیب اسے کچھ نہیں کہتی۔ تنقید لوگوں کو ادب کے واسطے سے مہذب بنانے کی کسی بھی سرگرمی کو قابل اعتنا نہیں سمجھتی۔ لیکن ہر تہذیب کی طرح، ہر ادبی روایت کی جڑیں بھی ایک الگ زمین میں پیوست ہوتی ہیں۔ اس زمین کا ذائقہ، جغرافیہ، موسم، ماحول، رسمیں اور روایتیں، مجبوریاں اور معذوریاں، دکھ سکھ اس کے اپنے ہیں۔ مختلف انسانوں میں احساسات اور جذبات مشترک ہو سکتے ہیں۔ مگر طرز احساس اور نظام جذبات ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ اور اسی سطح پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو تہذیبیں یا دو ادبی روایتیں بھی یکساں نہیں ہوتیں۔ مانا کہ ہر ادبی تجربہ، بنیادی طور پر انسانی تجربہ ہے اور انسان ہی وہ محور ہے جس کے گرد ہر روایت گھومتی ہے۔ مگر وہ ایک شے جو انفرادیت کہلاتی ہے اور احساس و عمل کی ایک الگ منطق بناتی ہے، اسی کے مرکز سے وہ لکیر بھی پھوٹتی ہے جو انسان اور انسان میں فرق کر سکے۔ جو مختلف تہذیبوں کی الگ الگ پہچان کر سکے، جو مغرب کی روایت اور مشرق کی روایت کا مفہوم مختلف سطحوں پرمتعین کر سکے، یا جو قدیم کو جدید سے جدا کر سکے۔ تعمیم سے تخصیص کا راستہ اسی سیاق و سباق میں نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔
گئے زمانوں میں توخیر تہذیبوں اور روایتوں کے امتیازات بہت نمایاں تھے اور ان کے مابین، انسانی سطح پر ہم رشتگی کے باوجود ایک فاصلے میں یقین عام تھا لیکن ہمارا عہد جس کے کاندھوں پر بین الاقوامی اور عالمی انسان کا بوجھ سوار ہے، اس عہد کے سامنے بھی پہلی، دوسری اور تیسری دنیا کے بنتے بگڑتے تماشے ہیں اور یہ ساری دنیا ئیں ایک الگ تاریخ اور جغرافیہ رکھتی ہیں۔ تجربے، احساس اور فکر کا اپنا الگ محور بھی رکھتی ہیں۔ بیسویں صدی کے ہندوستانی ادب کا جائزہ لیتے ہوے نامور سنگھ نے (اپنے ایک حالیہ مضمون میں) لکھا تھا کہ ادب میں اب امریکہ اور یورپ کی بالادستی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ آئندہ ادبی سرگرمیوں کے اصل مراکز امریکہ اور یورپ نہیں بلکہ لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہوں گے۔ نامور سنگھ کا خیال ہے کہ امریکی اور یورپی نظریہ سازوں نے اس اندیشے کے امکان سے بچنے کی خاطر کچھ نئے مفروضات عام کئے ہیں، جن میں سے ایک مفروضہ تھرڈ ورلڈ لٹریچر بھی ہے۔
اصل مسئلہ پہلی، دوسری، تیسری دنیا کے ادب کی تقسیم کا نہیں، شناخت کا ہے اور اس شناخت کے اصول مرتب کرنے کا مرکزی وسیلہ تنقید بنتی ہے۔ چنانچہ تیسری دنیا کی حسیت کے عناصر کی طرح، تیسری دنیا کے ادب کی تعریف اور تفہیم کے دائرے متعن کرنے والی تنقید کے عناصر بھی الگ ہوں گے۔ اب ذرا پیچھے مڑکر دیکھتے ہیں۔ محمد حسن عسکری نے ہندوستانی ادب کی پرکھ کے عنوان سے اپنے ایک کالم (اکتوبر ۱۹۴۶ء) میں لکھا تھا،
’’اردو کے تنقیدی شعور کا اندازہ کرنے کے لئے صرف شاعروں کی واہ واہ تک محدود نہیں رہنا چاہئے۔ بلکہ (گزشتہ زمانوں کے) بڑے بڑے شاعر اور تذکرہ نگاروں کی رائے کا بھی غور سے مطالعہ کرنا چاہئے۔۔۔ اس شعور کی تشکیل توا صولوں کی شکل میں نہیں ہوئی، مگر اس کی شہادتیں ہمیں بڑے بڑے استادوں کی اصلاحوں میں، ان کے دوچار جملوں میں، جو روایت کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں، اور تذکرہ نگاروں کے انتخابات میں ملتی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں شعر کی پرکھ کے معیار وہی تھے جو ایک مہذب قوم کے ہونے چاہئیں۔ میر کی شاعری کو پسند کرنا اور انہیں خدا ئے سخن کا لقب دینا ہی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں صرف زبان وبیان کی خوبیاں ہی قابل توجہ نہیں تھیں بلکہ اخلاقی، ثقافتی اقدار بھی بڑی شاعری کے لئے لازمی سمجھی جاتی تھیں۔ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔
ناسخؔ کے زمانے میں لفظ پرستی رائج ہو گئی تھی تو کیا؟ معتقدین کے کارنامے تو نظروں کے سامنے تھے اور یہ اتنی زبردست چیز تھی کہ اس سے چشم پوشی ناممکن ہے۔ میرؔ کے متعلق یہ مصرعہ لکھ کر گویا ناسخ نے یہ صاف اعتراف کر لیا ہے کہ بڑی شاعری کے لئے محض مراعاۃ النظیر اور مناسبت لفظی کافی نہیں بلکہ ہم اس سے جذبات کے ایک خاص کلچر کا مطالبہ کرتے ہیں اور زندگی کے متعلق ایک بلند اور سنجیدہ نقطہ نظر مانگتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو ہمارے تنقیدی معیار (وہ غیر شعوری ہی سہی) بڑی شاعری کے لئے چند ثقافتی اور جذباتی اقدار لازمی ٹھہرا تے ہیں۔ دوسری طرف بیان اور اسلوب کے بھی ایسے اصول پیش کرتے ہیں جو ہر ترقی یافتہ، زبان اور ادب میں رائج ملیں گے۔‘‘
تشویش اور حیرت کامقام ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے جدید الفکر ادیب بھی پائے جاتے ہیں جنہیں ادب کے معاملات میں اقدار کا ذکر تک سننا پسند نہیں۔ گویا کہ ادب یا تنقید کی اخلاقی اساس ادب اور تنقید کو کچھ اور بنا دیتی ہے۔ مگر اقدار مواعظ کی پوٹ نہیں ہوتیں کہ تجربیت اور عقلیت پرستی کا وظیفہ پڑھنے والوں کے احساسات کو چھو بھی نہیں سکتیں۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ تہذیب اور ثقافت یا تخلیقی اور جمالیاتی وجدان کی سطح پر عقلی رویے کی آمیزش سے بھی اقدار کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسانی تجربہ اپنے نتائج کی روشنی میں بالآخر ایک اخلاقی سوال سے مربوط ہوتا ہے۔ پھر عقلیت کی ایک اپنی اخلاقیات بھی ہوتی ہے۔ ہم اسے سانس کی طرح یکسر معروضی اور قائم بالذات نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کے سو فی صدی غیر جانب دار ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔
چنانچہ اقدار کے تصور سے خالی رہ کر نہ تو ادب ادب بن سکتا ہے نہ تنقید کسی معنی خیز انسانی سطح کو دریافت کر سکتی ہے۔ قدر ان معنوں میں عقیدے سے بڑی چیز ہے کہ اسی کے واسطے سے کسی امکان اور عقیدے کا دائرہ ہمارے احساسات اور بصیرتوں کے گرد پھیلتا ہے۔ یہاں مذہبی اور غیر مذہبی کی قید نہیں۔ قدیم ہندوستان میں اس سدھانت کا پورا ڈھانچہ ایک پوری تہذیب کے طرز احساس کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس طرز احساس کا تعلق انسان کو اس کے عمل اور رد عمل کی تمام صورتوں کے ساتھ قبول کرنے کے تصور سے تھا۔ انسانی حقیقتوں سے دامن کشاں اور صرف اپنے سائے میں سانس لیتی ہوئی اپنے سحر میں گم اور آپ اپنے بوجھ سے نڈھال تنقید تنقید ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کوئی اثر نہ تو ادب پر پڑتا ہے، نہ زندگی پر۔
ہماری قوم کا ادبی شعور دراصل اس کے مجموعی تہذیبی شعور کا ایک حصہ تھا۔ اسی لئے فن اظہار کی مختلف نوعیتوں کا تجزیہ کرتے وقت وہ انسان کے بنیادی جذبوں کو، عام زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی طرف اس کے مختلف رویوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ انسان سے ان کا رابطہ محض علمی نہیں تھا۔ مغربی علما کے مقابلہ میں ان کے اس امتیاز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ مختلف اشیا اور مظاہر کے مفہوم تک ایک دوسرے کے سیاق میں پہنچتے تھے۔ ان کے الگ الگ تجزیے سے زیادہ، ان کے داخلی رابطوں سے شغف رکھتے تھے۔ تجزیے پر تجربے کو ترجیح دیتے تھے چنانچہ ان کی منطق بھی تاثر آفرینی کے عمل کی منکر نہیں ہوتی تھی۔ شعور کو احساس سے اور آگہی کو جذبے سے ہم آہنگ کرتے ہوئے جھجکتی نہیں تھی۔
ان باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں ادب اور تنقید اور تہذیب اور روایت کے معاملات میں علیحدگی پسندی کی وکالت کررہاہوں۔ دنیا پہلے ہی سے بہت خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں، عالمی تہذیب اور عالمی ادبی معیار اور اقدار کا تصور کتنا ترقی یافتہ محسوس ہوتا ہے! انسان کی اجتماعی جدوجہد صدیوں کا جانکاہ سفر طے کرنے کے بعد اس نشہ آور احساس تک پہنچتی ہے۔ لیکن زبان اور ادب کی سطح پر متعصبانہ علیحدگی پسندی اگر عیب ہے تو صرف اس خیال سے کہ تہذیب اور تنقید کے بارے میں ہمارا تناظر وسیع اور ہر طرح کی حدبندی سے عاری ہو۔
اپنی روایت کے تشخص سے، روگردانی بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ہر ادبی اور تہذیبی روایت کی روح ایک مخصوص علاقے اور معاشرے کی صدیوں کی تاریخ کا ترکہ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق اپنے ماحول اور خطے کے جغرافیائی حالات، ’رسوم‘، روایات، مظاہر اور موجودات سب سے ہوتا ہے۔ یہی روح ہر معاشرے کی Life-line ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی خارجی پرتوں میں وقت کے ساتھ رونما ہونے والے تغیرات کے باوجود، ہر عہد میں اس کا تسلسل باقی رہتا ہے اور یہ متروک نہیں ہوتی۔ داخلی وحدت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنی انفرادیت کا تحفظ کرتی ہے۔
تذکرہ نویسی کے دور میں شعوری طور پر خواہ تنقیدی اصولوں کی تعیین اور معیار بندی کے ہنر سے لوگ واقف نہ رہے ہوں، لیکن ادب کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کا ایک تصور انہیں اپنی تہذیب نے بے شک فراہم کیا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو انگریزی زبان اور مغربی علوم کی یلغار سے پہلے ہماری اپنی کوئی جمالیات بھی نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ’’پیروئی مغربی‘‘ کے دور میں آزاد، حالی اور شبلی کو ادبی افہام و تفہیم کے نئے تصورات کی آبادکاری کے لئے کوئی خالی اور سنسان علاقہ نہیں مل گیا تھا۔ ان ’’نئے‘‘ تصورات کے شور شرابے میں کچھ پرانے تصورات کی سرگوشی بھی سنی جا سکتی تھی۔ شعر العجم کی چوتھی جلد کے ابتدائی نوے (90) صفحات سے قطع نظر، حالی اور آزا د کے مصلحانہ جوش کے باوجود، ان کی تحریروں میں بھی پرانے مذاق اور معیار کی گونج شامل ہے۔ ایسا نہ ہوتا توان کا معاشرہ ان کااثر قبول کرنے اور اپنا ردعمل ظاہرکرنے کی طاقت سے یکسر محروم ہوتا۔
اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں تہذیبی اور فکری نشاۃ ثانیہ کی حقیقت اپنی جگہ پر، مگر ان صدیوں کے پیچھے ان کا اپنا ماضی بھی تھا اور اجتماعی طرز احساس کی طرح اجتماعی ماضی کو بھی اپنا لاؤ لشکر سمیٹنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لاکھ سمیٹنے پر بھی اس کاکچھ نہ کچھ حصہ چھوٹ ہی جاتا ہے۔ کبھی نئے احساسات میں جذب ہونے کے لئے، کبھی ایک متوازی، متحارب قدر کے طور پر۔
جیلانی کامران نے تنقید کا نیا پس منظر کے عنوان سے اس ضمن میں کچھ معنی آفریں نکتے اٹھائے تھے۔ ان کی طرف آنے سے پہلے یہاں یہ عرض کردوں کہ مجھے ذاتی طور پر جیلانی کامران کی شاعری بہت پسند رہی ہے، مگر ان کے شعری تصورات سے اور ادب و تہذیب کے بارے میں ان کے بیشتر مقدمات سے اختلاف رہاہے۔ تاہم ہمارے معاصرین میں ان کی حیثیت ایک نہایت مربوط اور مستقل مزاج نظریہ ساز ادیب کی ہے۔ اور یہ مضمون جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، جیلانی کامران کی مخصوص ترجیحات کا ترجمان ہوتے ہوئے بھی زیر بحث مسئلے کے سیاق میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مختصر لفظوں میں ان کے پیش کردہ نکات یہ ہیں،
(۱) ہر ادب اپنی تہذیب کی ذمہ داریوں سے پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح اپنی وساطت سے اپنی تہذیب کے بلند ترین مقاصد کی نشاندہی کرتا ہے۔
(۲) کرۂ ارض پر ایک انسان نہیں، لوگ رہتے ہیں اور زمین کا نقشہ تہذیبوں کی تقسیم سے پیدا ہوتا ہے۔
(۳) ادب کا تنقیدی مطالعہ تہذیبی پس منظر کی نفی سے نہیں بلکہ اسی پس منظر کے اقرار سے ممکن ہوتا ہے۔
(۴) سند کی تلاش میں اپنے بجائے پرائے تہذیبی منطقے میں گزر کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اپنے اساتذہ کی سند غیر مستعمل ہونے کے باعث بے کار ثابت ہو چکی ہے۔
(۵) علم تنقید کے سارے راستے معافی تک پہنچتے ہیں اور معانی تک پہنچنے کا راستہ صرف ان تہذیبی منطقوں ہی سے گزر کرتاہے جن کے درمیان معانی نے تْخلیقی شکل و صورت اختیار کر لی ہے۔
(۶) کلاسیکل کے معنی اس کے اپنے تہذیبی وطن کے بغیر واضح نہیں ہوتے۔
(۷) (پرانے ادب پاروں میں) معانی کے مقدس مقام تک پہنچنے کے لئے عجز اور تحمل کا ہونا ضروری ہے۔ جن بزرگوں نے ان ادب پاروں کو تخلیق کیا تھا، وہ نہ صرف ہم سے جدا ہو چکے ہیں، بلکہ وہ فکری دنیا بھی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ اور ہم ان ادب پاروں کی دنیا میں صرف اجنبی کی حیثیت میں داخل ہو سکتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ پرانے ادب پاروں کی بابت ہمارے رویے میں بیگانگی کا پہلو، جس کی طرف جیلانی کامران نے یہ کہتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ ’’وہ فکری دنیا ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔‘‘ ایک خاصہ پیچیدہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ ایک سطح پر ہماری اجنبیت اگر حقیقت ہے تو دوسری سطح پر یہی اجنبیت ایک MYTH یا مفروضہ بھی ہے۔ اور اسی کشمکش کے واسطے سے حالی سے لے کر اب تک کی اردو تنقید کو درپیش ایک سوال سامنے آتا ہے۔ یہ سوال بیک وقت ہماری تہذیبی روایت اور ہماری ادبی و تنقیدی روایت دونوں سے متعلق ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی تنقید کے باہمی رشتوں اور ان کے مابین رونما ہونے والے تصادمات کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالی اور آزاد کے پورے نظام فکر میں ایک طرح کا روحانی پیچ و تاب اور فکری اضطراب کا جو عنصر نمایاں نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ سے الجھتے ہوئے ایک عہد سے وابستہ اسی سوال کو سامنے لاتا ہے۔
آج کی تنقید اس سوال کا حق اسی صورت میں ادا کر سکتی ہے جب وہ اس سوال کو آج کی زندگی کے سیاق میں رکھ کر دیکھ سکے۔ مزید برآں، جس صورت حال سے ہماری اجتماعی زندگی دوچار ہے، اس میں کسی ادب پارے کی معنویت سے زیادہ اہم سوال خود ادب کی معنویت کاہے۔ محمد حسن عسکری نے ۱۹۴۴ میں ہمارے ادبی ماحول کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا تھا کہ ’’ہمارا شعور قلعہ بند ہوکر بیٹھ گیا ہے۔ نہ تو ہتھیار ڈالنے کی ہمت ہے نہ باہر نکل کر لڑنے کی۔ آج کل ہماری جو بھی ادبی سرگرمیاں ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تعطل کی حفاظت کی جائے۔‘‘ (مضمون، تنقید کا فریضہ) تقریباً چالیس برس بعد بھی، آج صورت حال کچھ زیادہ نہیں بدلی ہے۔ ماضی کا ادب ہمیں اس لئے اجنبی دکھائی دیتا ہے کہ اس کے تہذیبی حوالوں سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، اور مروجہ ادبی تصورات سے ہماری عام بیزاری کا سبب یہ ہے کہ ہم ان تصورات میں اور اپنے تجربوں میں کسی بامعنی رشتے کے قیام کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔
جدید تنقید نے ادب اور قاری کے درمیان پل کم بنائے، دیواریں زیادہ کھڑی کی ہیں۔ تنقید کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب کے واسطے سے وہ اجتماعی اور انفرادی سطح پر انسان کے زندہ مسئلوں کو سمجھے اور ان سے بحث کرے۔ تخلیقی زبان ان مسئلوں کا صرف حوالہ ہے، آپ اپنا مقصود نہیں۔ ان نکتوں کا ادراک تو حالی، شبلی اور آزاد کو بھی تھا۔ مگر بیسویں صدی کی چوتھی پانچویں دہائی تک آتے آتے ہماری تنقید کچھ ایسے ٹھس لوگوں کا تختہ مشق بھی بن بیٹھی، جو اپنے شعور کی تربیت کے لئے مغرب کا ادب پڑھنے کے بجائے صرف مغربی اصولوں کی آگاہی کو کافی سمجھتے تھے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس آگاہی کا مقصد بھی ان کے نزدیک صرف یہ تھا کہ (مشرق) اردو کی ادبی روایت کے ماضی وحال کے بارے میں کچھ فیصلے صادر کئے جائیں۔ اپنی روایت کو اس راستے پر ہانک دیا جائے جو مغربی معیاروں کے تصور سے آباد تھا۔ ان کے نزدیک اپنے زمان ومکاں کے جنجال سے نکلنے کی یہی ایک امکانی صورت تھی۔
سحر کی ایک کیفیت میں مبتلا، وہ تو بس خیالوں میں پھر رہے تھے۔ نہ تو ان کے پانو اپنی زمین پر تھے کہ تنقید کو مجرد اصولوں کی دستاویز کے بجائے قاری کے لئے ایک زندہ تجربے کی حیثیت دیتے اور اپنے عہد کے ادب میں اور اس عہد کی زندگی سے رابطوں کا شعور عام کرتے، نہ ہی ان کے وجود کی جڑیں اپنی تہذیب اور تاریخ میں اس طرح پیوست تھیں کہ اپنی روایت کو ایک سلسلے کی صورت دے سکتے۔ نتیجہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے ماضی بھی نکل گیا حال بھی۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کلیم الدین جیسے جلیل القدر نقاد کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ (بہ قول اسپنگلر) ’’ایک کلچر دوسرے کلچر کا طرز احساس مستعار نہیں لے سکتا۔‘‘ اور ہر کلچر اپنے اظہار کی جو شکلیں ترتیب دیتاہے، وہ لازمی طور پر دوسرے کلچر کے لئے بھی بامعنی نہیں ہوتیں۔
مغرب کے تنقیدی اصول اور افکار مغربی ادب کی ایک لمبی روایت کا عطیہ تھا اور اس روایت کی تشکیل ایک مختلف اور ہمارے لئے اجنبی تہذیبی پس منظر کے واسطے سے ہوئی تھی۔ اس سے وابستہ نظام اقدار مغرب کا تھا، حسی اور جذباتی رویے مغرب کے تھے۔ انسانی سطح پر ہمارے لئے یہ قدریں، روایتیں اور رویے بہت اہم اور بامعنی سہی، مگر بہر حال، یہ ہماری اپنی میراث نہیں تھی۔ اردو کی ادبی روایت کا ظہور جس ہند اسلامی تہذیبی، معاشرتی، فکری سطح پر ہوا تھا، وہ تنقید کے ایک الگ نظام، ایک مختلف زاویہ نظر اور اقدار کے ایک مختلف تصور کے واسطے سے سمجھی جاسکتی تھی۔ تنقید کا فریضہ محض وضاحت نہیں، ادب پڑھنے پر آمادہ کرنا بھی ہے۔ چنانچہ ایسی تنقید جس کے فکری، جمالیاتی منطقے میں اور اس تنقید کا موضوع بننے والی ادبی روایت میں معاشرت حائل نہ ہو، اس ادبی روایت کی تہذیبی قدروں کے سیاق میں ہی اس کی معنویت کا سراغ لگاتی ہے۔
ادب کو سمجھنا، انسان کے ازلی اور ابدی تجربوں کو سمجھنا تو ہے، مگر ایک مخصوص معاشرتی حوالہ سے۔ اسی لئے ایک خاص تہذیبی روایت کے ترجمان ادب کے موضوعات کی چھان بین ہی نقاد کے لئے کافی نہیں ہوتی، ان موضوعات کا رشتہ اس کی تہذیب سے کن سطحوں پر استوار ہوتا ہے؟ یہ سطحیں کن اقدار کی تابع ہوتی ہیں؟ ان قدروں کے انفرادی اور اجتماعی شناس نامے کیا ہوتے ہیں۔ ان سوالوں میں الجھے بغیر ادیب، نقاد اور قاری کے تکون کی تکمیل نہیں ہوتی۔
روایت اور طرز احساس کی تبدیلی صدیوں پر پھیلے ہو ئے ایک خاموش عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جدید تہذیبی نشاۃثانیہ کے ساتھ اٹھارویں صدی میں ہمارے یہاں روشن خیالی کی ایک لہر ٓائی۔ ایک دوسری لہر، عقلیت کی انیسویں صدی میں ٓائی۔ سائنس ٹکنولوجی کی ترقی نے ہمیں بتایا کہ ’’مغرب کی ایک شائستہ قوم‘‘ سے ہم کتنے پیچھے ہیں۔ مگر روشن خیالی، عقلیت، تعمیر وترقی کا ایک تصور ہماری تہذیب کے پاس بھی تھا۔ ایسانہ ہوتا تو مغربی علوم افکار، وسائل کی حصولیا بی نے ہماری تہذیب اور ادبی سرگرمیوں کا مزاج اور محور بھی یکسر تبدیل کر دیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اینگلو انڈین ادب کی ایک اصطلا ح کے چلن اور مغرب پرستی کی ایک مبالغہ آمیز طلب کے باوجود، اجتماعی طور پر ہمیں اپنی اس نارسائی کا شکر دا کرنا چاہئے کہ ہم مغربی معیاروں کے مطابق مہذب اور ترقی یافتہ ہونے سے بال بال بچ گے۔
مگر غور طلب واقعہ یہ ہے کہ اسی کشمکش اور تصادم سے بھرے ہوے ماحول کی کوکھ سے غالبؔ کی شاعری بھی تو سامنے آئی۔ غالب کتنے قدیم ہیں اور کتنے جدید، یہ بحث پھر کبھی۔ البتہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اردو کی ادبی روایت، ہماری تخلیقی Genius اور اجتماعی تاریخ کے سب سے روشن نشانات میر، غالب، اقبال، انیس سے لے کر پریم چند اور قرۃ العین حیدر تک، جس تہذیبی اور معاشرتی ماحول اور احساسات، اقدار اور افکار کے جس نظام سے مربوط ہے، اس کا خاکہ اسی سرزمین پر مرتب کیا گیا۔ ان کے یہاں مظاہر اور موجودات کی جو شکلیں ابھرتی ہیں وہ صرف شے اور مظہر نہیں ہیں۔ ایک مخصوص تہذیبی تصور کے اشارے بھی ہیں۔
محمدحسن عسکری کے جس مضمون کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اسی میں ایک بات یہ بھی کہی گی ہے، ’’میر حسنؔ کی مثنوی ہارڈی کا ناول نہیں ہے۔ دونوں کا تہذیبی پس منظر الگ ہے اور ہر تہذیب کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فن کی شرائط آپ مقرر کرے، یعنی انسان کو اپنے طریقے سے سمجھے۔‘‘
سب سے بڑا سوالیہ نشان جو اردو کی جدید تنقید پر ہوتا ہے، یہی ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے مناسبت رکھنے والی فنی شرطوں سے بے نیاز ہوتی جا رہی ہے۔ مغرب کی تقلید میں نہ تو وہ مغربی بن سکی نہ ہی مشرقی طرز احساس کے فروغ اور تحفظ کا وسیلہ فراہم کر سکی۔ یہ ڈائلما (Dilemma) ہمارے ادب اور ہماری تہذیبی روایت دونوں کو درپیش ہے۔ آخر کوئی تووجہ تھی کہ حالی، آزاد سے اختلاف کے باوجود، ان کا تنقیدی محاورہ ان کے عہدکے لئے ناقابل فہم اور غیر دلچسپ نہیں تھا۔ ادراک اور احساس کی سطحوں اور نوعیتوں میں تبدیلی کے باوجود ان کی بصیرتوں کا رشتہ اپنی تہذیبی اور ادبی روایت سے ٹوٹا نہیں تھا۔ مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادب لکھنے والے اور ادب پڑھنے والے بتدریج موجودہ تنقید کے محاورے اور دائرے سے باہر نکلتے جاتے ہیں۔
دونوں میں تنقید کی طرف سے ایک بے اطمینانی مشترک ہے۔ اپنے طرز احساس میں نمو کی طاقت کو پروان چڑھانا یا ان کی مدافعت کرنا تو دور کی بات ہے، مستعار ضابطوں، قدروں اصولوں کی یلغار میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو بس احساسات کو کند کرنے کی۔ لگتا ہے کہ ہم صرف ذہنی سطح پر زندہ رہنے کو کافی سمجھنے لگے ہیں اور جیتے جاگتے تجربوں سے مالا مال زندگی ہمارے لئے اپنا مفہوم کھو بیٹھی ہے۔ ہمارا انہماک اگر کچھ ہے تو ایک بے روح سرگرمی میں اور ہم بے چین اس لئے نہیں ہوتے کہ ابھی نقادوں کا ایک قبیلہ تو باقی ہے جو ہماری تنقید کی کتابیں اور مضامین کم سے کم ضرورتاً پڑھ لیتا ہے۔
مغرب کی تہذیبی اور ادبی قدروں اور اصولوں کا عمل دخل ہماری اجتماعی زندگی میں اس وقت شروع ہوا جب ہماری اپنی روایت کا سفر ایک تکمیل یافتہ موڑ تک پہنچ چکا تھا۔ ایسی صورت میں مغرب سے اخذ و استفادہ خواہ ہماری مجبوری بھی رہا ہو مگر اس سے زیادہ ایک طرح کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی۔ ہم اپنی مرضی سے اپنا انتخاب کر سکتے تھے اور اپنی روایت یا اپنی اجتماعی سرشت کے یا امتیازی تقاضوں سے مناسبت رکھنے والے عناصر تک ہی، چاہتے تو خود کو محدود رکھتے۔ مگر نئے علوم کی حشرگاہ میں بے محابا کود پڑنے کا نتیجہ سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ ذہنی سرگرمی، لازمی طور پر، تہذیبی اور ادبی سرگرمی کا حصہ نہیں ہوتی! سو، شکایت دراصل مغرب سے نہیں، اپنے آپ سے ہے اور اپنے بے لگام تقلیدی رویے سے۔
نوٹ، یہ مضمون شعبۂ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام تنقید پر ایک سمینار (مارچ ۱۹۹۱) میں پڑھا گیا۔ اس مضمون کے حوالے سے سیمینار میں جو بحثیں ہوئیں اور جو سوال اٹھاے گئے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے،
(۱) ایک صاحب نے فرمایا کہ اس مضمون میں تہذیب کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، محدود ہے اور ایک مخصوص فکری ومذہبی روایت کا تابع۔ پاکستانی دانشور تہذیب کا بہت یک رخا تصور رکھتے ہیں۔ محمد حسن عسکری اور جیلانی کامران یا ہندوستان میں عبدالمغنی جیسے لوگوں کے یہاں تہذیب کا جو تصور ملتا ہے، اس تصور سے کتنا مختلف ہے جو ہم ڈاکٹر عابد حسین یا پروفیسر محمد مجیب کے یہاں دیکھتے ہیں؟ مابعد ساختیات کے بارے میں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ وہ انسان کی نفی کرتا ہے؟ تہذیبی علیحدگی پسندی کا میلان اردو کی ادبی روایت کے تہذیبی سیاق کو بہت سمیٹ دیتا ہے۔
(۲) ایک اور صاحب نے کہا تھاکہ تہذیب تو ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم جب اردو زبان اور ادب کے واسطے سے تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اشارہ کس تہذیب کی طرف ہوتا ہے؟
(۳) یہ بھی کہا گیا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور عالمی انسان کاہے۔ چنانچہ ہمارا تہذیبی حوالہ بھی اب بدل چکا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایک بین الاقوامی عالمی تناظر میں اس مسئلے کا تجزیہ کیا جائے۔ علاوہ برایں، اب تو صورت حال یہ ہے کہ ہمارا عہد لا=انسان کا عہد ہے۔ یعنی کہ انسان کا اپنا کوئی مفہوم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں تہذیب سے سروکار محض ایک مفروضہ ہے۔
(۴) ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ ہمارے لئے لفظ اور انسان کا رشتہ زیادہ اہم ہے، یا لفظ اور تہذیب کا رشتہ؟ تخلیقی لفظ کا بنیادی سروکار فرد سے ہوتا ہے نہ کہ اجتماع سے۔
(۵) اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ لفظ سماجی مظہر ہے۔ چنانچہ ہر لفظ کسی نہ کسی اجتماعی تجربے سے مربوط ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ سمجھنا کہ تہذیب سے تحقیق و تنقید کا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے، صحیح نہیں ہوگا۔
(۶) ایک اور مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ ان دنوں ہر ادبی روایت اور ہر علاقے کے ادب میں مذہب کی طرف میلان کا اظہار نمایاں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب تہذیب کا تصور ایک بنیادی مذہبی فکر سے نسبت رکھتا ہو؟
(۷) ادبی تحقیق، تنقید اورادب فہمی کے معیاروں میں اور ادب پڑھنے والوں میں فاصلے کا احساس جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک سامع نے یہ کہا کہ ادب کو سمجھانے کے لئے جو باریک بینی اور بصیرت درکار ہوتی ہے وہ روز بروز محدود و مفقود ہوتی جارہی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے اپنی نارسائی پر قابو پانے اور اختصاصی مہارت بہم پہنچانے کی۔
(۸) کچھ ایسے نکات بھی سامنے آئے (مضمون پر گفتگوکے دوران) جن سے فکر کی غیرمعمولی سادہ لوحی ظاہر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہ مضمون میں تہذیب اور کلچر کے فرق کی وضاحت بھی کر دینی چاہے تھی یا یہ کہ مشرقی تہذیب کے تصور کا بہت وسیع اور ہمہ گیر اظہار ہمارے عہد میں ادب سے متعلق لکھی جانے والی کئی کتابوں میں ہوا ہے۔ یا یہ کہ ہماری تہذیب کے خارجی مظاہر اور رنگ ہماری ادبی روایت میں آج بھی صاف جھلکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔
ان مباحث کی روشنی میں کچھ وضاحتیں اس طرح ہیں،
ہر ادب کی ایک بنیادی روایت ہوتی ہے اور ایک مخصوص تہذیبی حوالہ۔ پاکستانی ادیبوں اور دانشوروں میں بے شک ایسے اصحاب کی کمی نہیں جو تہذیب کے تصور کو اپنے سیاسی مقاصد سے آزاد نہیں کر پاتے اور بعض فکری، تہذیبی، جمالیاتی رویوں کی تعبیر میں اپنے تعصبات اور ترجیحات کے پابند ہوتے ہیں۔ اس ذہنی اور جذباتی صورت حال کے شکار اصحاب ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پاکستانی یونیورسٹی کے ریکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ فرایڈ، آئن سٹائن، ڈارون اور کارل مارکس کے نظریات غیر اسلامی ہیں۔ جب اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سوچ بچار کا یہ انداز رواج پاجائے تو علم اور تہذیب اور ادب کے حشر سے ڈرنا چاہئے۔
اسی طرح پاکستان ہی کی ایک یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نے جمالیات کے موضوع پر دو بلکہ تین ضخیم جلدیں مرتب کرنے کے باوجود ایک مجموعی نتیجہ یہ برآمد کیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جمالیاتی نظام کے جو نمو نے سامنے آئے ہیں، ان میں قابل ذکر بس تین ہیں۔ ایک تو قدیم یونانی، دوسرے عہد وسطیٰ کی یوروپی جمالیات اور تیسرے اسلامی۔ گویاکہ چین، جاپان، ہندوستان اس میدان میں کورے ہیں۔ انہوں نے صرف گھاس کھودی ہے اور بھرت منی کی ناٹیہ شاستر کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس ضمن میں ایک پاکستانی عالم کو وادی سندھ کی تہذیب کے مطالعے میں عربی رسم الخط کے وجود کا سراغ بھی مل گیا تھا۔
اس طرح کی تخلیق اور علمی دریافتوں سے ہمارے ملک کے بعض جید علما کا دامن بھی خالی نہیں ہے۔ تہذیب کی کسی سنجیدہ بحث میں ایسوں کا تذکرہ بے سود ہے۔ البتہ عسکری اور جیلانی کامران کے تہذیبی تصورات کو اس نوع کے کسی دائرے میں رکھ کر دیکھنا بد مذاقی بھی ہے اور ایک گہری بے بصری کی دلیل بھی۔ عسکری، جیلانی کامران اور عبدالمغنی کانام ایک سانس میں لینا بھی محاورۃً سب دھان ستائیس سیر کے مترادف ہے۔ عسکری کے سلسلے میں تو غلط فہمی ترقی پسند اور غیر ترقی پسند ہر حلقے میں خاصی جڑ پکڑ چکی ہے۔ اس حد تک ان کی فکر کے ارتقا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں رونما ہونے والے واضح تغیرات تک کولوگ بڑی آسانی سے نظر انداز کر جاتے ہیں۔
اس مضمون میں تہذیبی تصورات کی تاریخ نہیں بیان کی گی ہے۔ ایسا کیا جاتا تو پھر ڈاکٹر عابد حسین اور پروفیسر مجیب ہی نہیں رادھا کرشن، اروبندوگھوش اور جدو کرشنامورتی تک بہت سے لوگ زیر بحث آ سکتے تھے۔ مجھے تو ذاتی طور پر آچاریہ رجنیش کی کتابوں کے ذکر میں تامل نہیں کیونکہ میں نے صرف اس کی عیش کوشی کے قصے ہی نہیں سنے، اس کی کتابیں بھی پڑھی ہیں لیکن ہر ادبی روایت ایک کثیر الجہات وسیع اور پیچ در پیچ تہذیبی سیاق رکھنے کے باوجود اپنے کچھ مخصوص نشانات، فکر کا ایک مرکزی دھارا، ایک محور بھی رکھتی ہے۔ اردو کی ادبی روایت کے حوالے سے ان نشانات یا اس مرکزی دھارے کی پہچان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بقیہ تمام اوصاف اور عناصر جن سے اس روایت کا شناس نامہ ترتیب پاتا ہے، ہمارے لئے اپنی معنویت کھو بیٹھے ہیں۔ تہذبی علیحدگی پسندی اور کسی تہذیب کے NUCLEUS کی شناخت و تفہیم یا اس سے وابستگی کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہے۔
اسی طرح اپنی روایت کے بنیادی تہذیبی حوالوں پراصرار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تہذیب کے عالمی تصور سے دست بردار ہو گئے ہیں۔ نہ تو مقامیت آفاقیت کی ضد ہوتی ہے، نہ انفرادیت بین الاقوامیت کو مسترد کرتی ہے۔ شیکپیئر، کالی داس، حافظ، ٹیگور، ٹالسٹائے اپنی مقامیت اور انفرادیت کے واسطے سے اپنی آْفاقیت اور بین الاقوامیت تک پہنچتے ہیں۔
آفاقیت اور بین الاقوامیت کے فیشن ایبل تصور نے ادبی اور تہذیبی مقدمات میں ایک عجیب ابتذال کو راہ دی ہے۔ مجھے اپنی علاقائی زبانوں کے ادب میں تجربے، خیال اور بصیرت کی جو روشنی اور وسعت دکھائی دیتی ہے، اس کے سامنے انڈو اینگلین ادب کا بہت مشہور و معروف حصہ محض بچکانہ اور سنسنی خیز محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآں، حد سے بڑھی ہوئی ارضیت اور مقامیت پر اصرار میں بھی یہ خطرہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ تحریر کا فکری دائرہ بہت DATED اور بہت واقعاتی ہوکر نہ رہ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی ملحوظ نظر رہنا چاہے کہ اس مضمون میں تخلیق سے زیادہ تنقید اور تہذیب پر رابطوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نقاد جب آنکھیں بند کرکے کسی پرائے اور نامانوس تہذیبی مظہر میں معیاروں کو اپنا راہ نما بناتا ہے تو ایک تو اس تہذیبی سیاق سے خود کو الگ کر لیتا ہے جس نے متعلقہ تخلیق کو بنیاد مہیا کی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کے معیاروں میں اور تخلیق کو بنیاد مہیا کرنے والی تہذیب کے معیارو مزاج میں مطابقت نہیں رہ جاتی۔
رہا یہ سوال کہ ہندوستانی تہذیب کے کئی رنگ ہیں اور علاقائی سطح پر اس تہذیب کے اوصاف میں فرق و امتیاز کی لکیریں بہت واضح ہیں تو بے شک ایسا بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہے کہ جب ہم مشرقی تہذیب، مشرقی جمالیات یاہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی جمالیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس تہذیب اور جمالیاتی نظام کے بنیادی اور داخلی عناصر ہوتے ہیں۔ یہی عناصر رنگا رنگی میں ایک وحدت کی تعمیر کرتے ہیں اور زبانوں، نسلوں، علاقوں، عقیدوں کے فرق کو مٹائے بغیر بھی اختلافات میں ایک نقطہ اتحاد، ایک مرکزی تصور اور طرز احساس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارا جمالیاتی نظام، ہماری اپنی افتاد طبع، طرز احساس و اظہار ہمارے جغرافیے، ہماری تاریخ اور ہمارے اپنے اجتماعی رویوں کا تابع ہے۔
کسی ادب پارے سے ہمارے ذہنی، وجدانی، حسیاتی تقاضے کیا ہوتے ہیں اور ہم ان تقاضوں کی تکمیل کے کون سے آداب کو اپنے لئے مستحسن سمجھتے ہیں، انہیں نظر انداز کرکے کوئی بھی تنقید نہ تو ہمارے ذوق کی تربیت کر سکتی ہے، نہ ہم پر کسی جمالیاتی تجربے کا انکشاف کر سکتی ہے۔
بے شک، انسان کی مجموعی تاریخ و تہذیب کے ساتھ نموپذیر ہونے والے علوم اور افکار ہمارے ورثہ ہیں اوران کا ایک حصہ ایسا ہے جو من و تو کی ہر تفریق سے ماورا ہے۔ انسانی علوم و افکار کے اس حصے کی ضرورت اور اپنی صورت حال پر اس کے فراہم کردہ ضابطوں کے اطلاق سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی مخصوص روایت، افتاد طبع، حسی، جذباتی اور ذہنی ضرورتوں کو سرے سے پس پشت ڈال دیں اور کسی طرح کی نگہ انتخاب سے کام نہ لیں۔ مانا کہ کئی سطحوں پرمغرب ومشرق ایک ہو چکے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلے اور امتیازات بھی بہت ہیں۔ لارکن کو مشرق کے فکری اور حسیاتی نظام میں ایسی ہی چیز دکھائی دی تھی جو مغرب کو اپنی تمام کامرانیوں کے باوجود میسر نہیں ہوسکی اور مغربی تہذیب اس بے نام شے کی جستجو میں کب تک اور کیوں سرگرداں رہےگی، ہمیں اس پر غور کرنا چاہئے۔
مغرب میں مروج کسی ضابطہ علم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کے اکستابات ہماری روحانی یا ذہنی یا تخلیقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ یا یہ کہ اس علم کی وساطت سے ہم فہم و ادراک کے جس منطقے تک پہنچتے ہیں، اس تک رسائی کے لئے ہمیں علم و آگہی کے اس پیمانے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ ہمارے عہد کی تنقید کا سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ وہ افکار اور علوم کی نمائش بہت کرتی ہے، اس نمائش کے واسطے سے ہمیں کسی ایسے نتیجے کی شکل نہیں دکھاتی جو ہماری آزادانہ گرفت میں نہ آسکے۔ جب تک تنقید لکھنے والے تنقید پڑھنے والے اور ادب کی تخلیق کرنے والے کی WAVE-LENGTHS میں کچھ یکسانیت نہ ہو، یہ ساری تگ و تاز بے معنی ہے۔
اور یہ مطالبہ بھی اتنا ہی مہمل ہے کہ ادب پڑھنے والے یا تنقید پڑھنے وا لے اختصاص اور مہارت کے اس مرتبے کا حصول کریں جس پر تنقید فائز ہے۔ ادب، بہرحال ہماری اجتماعی سرگرمی اور ہمارے تہذیبی خلیے سے لاتعلق نہیں ہوتا۔ ادب کی تخلیق ایک انفرادی عمل سہی لیکن اس عمل کا دائرہ اس طرح کا اختصاصی (SPECIALIZED) دائرہ نہیں ہوتا جسے ہم سائنس دانوں یا سماجی علوم کے ماہروں کا یا کاریگروں سے منسوب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور انجینئر، شاعر اور افسانہ نگار بھی ہوسکتا ہے لیکن میڈیسن اور انجینئرنگ کی تحصیل میں ادب فہمی کوئی رول نہیں ادا کرسکتی۔ ادب کی تخلیق اور تفہیم کسی اختصاصی ریاضت ومشقت کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔
لفظ کو ایک سماجی مظہر یا زبان کو اجتماعی سرگرمی کا حاصل قرار دینا بالکل صحیح ہے۔ تاہم ہر نتیجے کی بنیاد پر یہ دلیل تو نہیں قائم کی جا سکتی کہ لفظ اور زبان کے استعمال کی ہر شکل ایک اجتماعی تجربے کا اظہار یا ایک ایسا عمل ہوتی ہے جس میں لکھنے والا اور پڑھنے والا یکساں طو رپر شریک ہوتے یا ہو سکتے ہیں۔ تخلیقی اظہار کی ہیئتوں کا کسی فرد کے شخصی رویے اور بصیرت سے جڑا ہوا ہونا برحق، مگر ادائے مطلب کے عام عمل میں زبان کا قاری کے لئے غیر فطری اور غیر ضروری حد تک نامانوس ہو جانا میرے خیال میں معیوب ہے۔ ہماری تنقید کو سیدھے سادے انسانی لہجے سے بے سبب دور نہیں ہونا چاہئے۔
تہذیب کے معاملے میں مذہب کے رول کا جائزہ بھی ٹھنڈے دماغ سے لیا جانا چاہئے۔ اول تو مذہب اور مذہب میں فرق ہوتا ہے پھر منظم مذہب اور مذہبی تجربے میں بھی فرق ہے۔ اسلامی ادب کی تحریک جو اچھے لکھنے والوں میں دور تک ساتھ نہیں چل سکی، اس کا سبب یہی ہے کہ تخلیقی فکر کسی بھی نظریاتی چیز کا بوجھ بس ایک حد تک سہار سکتی ہے۔ اس معاملے میں بدھ مت، ہندو مذہب، عیسائیت اور اسلام سب کا رول الگ الگ اور پنے مجموعی نظام عقائد اور افکار کے مطابق رہا ہے۔ کہیں تہذیب ایک خودرو پودے کی طرح عقائد، امکانات، فکر اور احساس کے اسالیب کی زمین سے دھیرے دھیرے نمودار ہوئی ہے، کہیں عقیدے اور ضابطہ فکر نے تہذیب کے کچھ پہلوؤں اور عنصروں کی پرورش کی ہے۔
یونانی اور ہندوستانی جمالیات کے پس پشت پوری پوری دیو مالاؤں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اسلامی فکر تشکیل کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی تخلیقی تخیل کی اس بے کناری سے بالکل الگ ایک مختلف ذہنی سطح اور اقدار کے ایک مختلف حوالے سے اپنی جمالیات کا تعین کرتی ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ کے واسطے سے جمالیاتی قدروں کا جو نظام سامنے آیا وہ اپنی سرشت کے لحاظ سے انڈو مسلم ہے۔ اب انڈو مسلم میں اور ہندوستانی واسلامی میں مفہوم کتنا مشترک ہوگا، اس کی تفصیل الگ ہے۔ البتہ اتنی سی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ انڈو مسلم (یا ہند+عربی+ترکی) تہذیب، تہذیب کے کسی علیحدگی پسندانہ تصور سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ اس مضمون کے مندرجات سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا ہے تو اس کا تجزیہ محض علمی اور ادبی سطح پر ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ نفسیات کا ہے۔
’’اسلامی فکر اور ہماری ادبی روایت‘‘ کے موضوع پر میں نے ایک مضمون کوئی دس بارہ برس پہلے (پروفیسر مشیر الحق مرحوم) کی فرمائش پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اسلامک اسٹیڈیز کی طرف سے برپا ہونے والے ایک سیمینار کے لئے لکھا تھا۔ یہ مضمون ان کی مرتبہ کتاب میں شامل ہے۔
اخیر میں ایک ڈیڑھ بات اور۔ لامساوی انسان کی تخلیقی اصطلاح یا اگاسی کے DE HUMANIZATON کے تصور سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ ہمارے عہد کی تہذیب بے چہرہ، انسانی عنصر سے یکسر تہی دامن ہو چکی ہے اور ن م راشد یا جوزے اور تیگا اگاسی اینٹی ہیومنسٹ تھے، درست نہیں۔ شاید انسانی سروکار کے بغیر آرٹ سے بشریت کے اخراج کا یا انسان کو لا کے مساوی سمجھنے کااندوہ پرور اور اضطراب آسا خیال ن م راشد اور اگاسی کے ذہن میں پیداہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ’’نفی سے اثبات کی تراوش‘‘ کا ایک تخلیقی اور فلسفیانہ طور ہے جس کی تفہیم و تعبیر بھی تخلیقی اور فلسفیانہ سطح پر ہی کی جا سکتی ہے۔
علاوہ ازیں اس سے بڑی خام خیالی اور کیا ہوگی کہ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اسی عہد کے افکار اور اقدار میں محصور تہذیب کو اپنے تہذیبی تصور کی اساس مان لیں۔ کسی بھی تہذیب کی ایک سطح وہ ہوتی ہے، جہاں اس کا سفر ایک ساتھ کئی زمانوں میں جاری رہتا ہے اور گزشہ سے آئندہ تک ایک سلسلہ قائم رہتا ہے۔ پھر میں تو اس حقیقت میں یقین رکھتا ہوں کہ تخلیقی آدمی خالی اپنے حال میں زندہ نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں حالیہ علوم پر ہی تکیہ کئے رہنا اور ادبی تہذیبی تصورات کے معاملے میں بس حاضر کی چوکھٹ پر ڈٹے رہنا چہ معنی دارد؟ ادب کی روایت اور تہذیب کی روایت روز کے روز تبدیل نہیں ہوتی۔