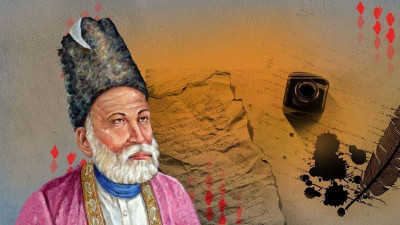منٹو اور نیا افسانہ
اردو افسانے کی تاریخ میں منٹو کی جگہ اتنی محفوظ اور ہمارے فکشن کی روایت میں ان کا مرتبہ اتنا مستحکم ہے کہ اب منٹو کے بارے میں محض تحسین اور عقیدت کے اظہار کا کچھ بھی مطلب نہیں نکلتا۔ اپنی حیثیت کا تعین خود منٹو نے جس طرح کیا تھا، اپنی مختلف تحریروں، یہاں تک کہ اپنے کتبے کی عبارت میں بھی، منٹو کے بیشتر قارئین نے اسے بے چوں و چرا تسلیم لر لیا ہے۔ منٹو سے متعلق زیادہ تر مضامین اور کتابیں اپنی بابت خود منٹو کی قائم کردہ رایوں کی تفسیر اور ان کا جواز مہیا کرتی ہیں۔ اس واقعے کے مطابق، منٹو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے اور اس سے متعق جو تازہ ترین کتاب میرے سامنے آئی ہے (آپ کا سعادت حسن منٹو ’منٹو کے خطوط‘ مرتبہ محمد اسلم پرویز، اشاعت، ممبئی، جنوری ۲۰۱۲) اس کے ساتھ مرتب نے ایک منٹو صدی کیلنڈر بھی شائع کیا ہے جس میں منٹو کو ’’دنیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار‘‘ کہا گیا ہے۔یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پرانا یا نیا کوئی بھی دوسرا افسانہ نگار منٹو کی اہمیت کا انکاری نہیں ہے۔ منٹو کے جیسے دعووں کی ہمت بھی کسی نے نہیں دکھائی، بعد کا کوئی افسانہ نگار منٹو کی جیسی شہرت اور مقبولیت بھی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ منٹو کے معاصرین میں ایک اوپندر ناتھ اشک نے ہی منٹو کو اپنے حریف کے طور پر دیکھا اور منٹو کے بعد آنے والوں میں، ریوتی سرن شرمانے اس کی سیاسی فہم اور غیر جانب داری پر نہایت دنداں شکن سوالیہ نشان قائم کئے۔ ہمارے ترقی پسندوں نے اس پرغلاظت نگاری اور رجعت پرستی کے الزامات عاید کئے (سردار جعفری، ترقی پسند ادب) منٹو کے کچھ نادان دوستوں نے منٹو کی انسان دوستی اور اخلاقی مساوات کے تصور کو پس پشت ڈال کر، اسے قوم پرست، وطن پرست اور شاید اپنی ہی قبیل کے میلانات سے سرشار اور مخلص مسلمان دکھانے کی کوشش کی، گویا کہ اسی بے ڈول منطق کا تابع جو ریوتی سرن شرما نے اپنے مضمون میں اختیار کی ہے۔مگر منٹو کے اپنے کچھ اختیارات اور قاری پر اس کے افسانوں کی طرف عاید ہونے والی کچھ شرطیں بھی ہیں، جنہیں سرے سے نظر انداز کر دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک بات جو اس کے قاری کو ہرحال میں یاد رکھنی چاہئے، یہ ہے کہ منٹو اول و آخر ایک افسانہ نگار تھا۔ اپنے عہد کا مؤرخ، وقائع نویس، فلسفی یا آئڈیا لاگ نہیں تھا۔ اس کی حقیقت پسندی بھی ایک آرٹسٹ کی حقیقت پسندی تھی، کسی صحافی یا سماجی مبصر کی حقیقت پسندی نہیں تھی۔ یہ ایک فطری اور تخلیقی ذہانت سے مالامال آرٹسٹ کی حقیقت پسندی تھی، جو عام زندگی اور سچائی کو بھی، اپنی فنی احتیاج کے مطابق نئے سرے سے وضع کرتا ہے۔ منٹو کے احساسات میں کشمکش کا جو مستقل اندازہ دکھائی دیتا ہے، ایک دائمی اضطراب کی جو کیفیت ملتی ہے، اس کے اسباب آئڈیا لوجیکل اور سیاسی نہیں ہیں۔منٹو کا شعور جس تناظر کی تہہ سے برآمد ہوا ہے وہ اس کے تمام معاصرین، بالخصوص ترقی پسند افسانہ نگاروں کے شعور سے زیادہ کشادہ ہے اور اپنے قاری کی بصیرت سے ایک منفرد، نجی قسم کا تعلق بھی قائم کرتا ہے۔ تاہم، اس کی بڑائی کے اس اعتراف کے باوجود، افسانہ نگار منٹو کو یہ مربیانہ رویہ اور رعایت درکار نہیں ہے کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار بھی قرار دیا جائے، ہرچند کہ اپنے حق میں یہ فیصلہ خود منٹو نے کر لیا تھا۔ مگر تمام تر خوبیوں کے باوجود منٹو اس وژن سے محروم تھا جس کے بغیر کسی ادبی تخلیق میں عظمت کے عناصر رونما نہیں ہوتے۔ منٹو ہمارا سب سے مقبول افسانہ نگا ر ہے، بڑا visionary نہیں ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر پریم چند، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کا وژن، تخلیقی مقاصد اور ان کے فکری سرو کار منٹو سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم، منٹو کی انفرادیت اور مرتبے پر اس سے حرف نہیں آتا۔یہاں ایک اور افسانہ نگار محمد حسن عسکری کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، جنہوں نے منٹو کے امتیازات کا شعور ’’اردو افسانے کے اس سنہرے دور‘‘ میں شاید سب سے زیادہ عام کیا اور منٹو کی موت پر جذباتی ہوئے بغیر عام کیا۔ عسکری بجائے خود بھی ایک غیرمعمولی افسانہ نگار تھے، اپنے تمام ہم عصروں سے الگ نظر آنے والے۔ انہوں نے منٹو کی فکری ترجیحات کو بھی سب سے زیاد ہ سمجھا تھا کہ منٹو ہی کی طرح انسان کی جبلت اور فطر ت میں پیوست رویوں اور تجربوں اور تصورات سے انہیں بھی خاصی دلچسپی تھی اور وہ ان کی منطق کا شعور بھی اپنے دوسرے تمام معاصرین سے زیادہ رکھتے تھے۔ ’جزیرے‘ اور قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے، کے افسانے آج بھی منفر د دکھائی دیتے ہیں، منٹو کے طرز احساس سے دور پاس کی مناسبت رکھنے کے باوجود، منٹو کی طرح عسکری بھی انسان کے باطنی تموج اور معاشرتی اقدار اور رسوم کی تہہ میں کلبلاتے ہوئے جذبوں کی عکاسی کے معاملے میں بے خوف تھے۔مزید برآں، تقسیم اور فسادات کے پیدا کردہ ہیجانات، تشدد کی شعریات اور ہنگامی حالات میں انسانی عمل اور احساس کی غیر متوازن صورتوں کے سلسلے میں ان کی جیسی ذہین بصیرتوں تک کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ عسکری کی افسانہ نگاری، ان کے دوسرے فکری مشاغل اور علمی سرگرمیوں کی تہہ میں دب گئی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تقسیم کے دور کے ادب کی ترکیب اور تخلیق کے مضمرات کو انہوں نے جتنی گہری اور حساس نظروں سے دیکھا تھا، کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ایک مخصوص دورکے معاشرتی ہنگاموں سے قطع نظر، سیاسی اور سماجی علوم کے ماہرین کی منٹو میں روز افزوں دلچسپی سے کبھی کبھی یہ اندیشہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ منٹو کا افسانہ اہل علم کے اقتدار بے جا کا تابع ہوتا جا رہا ہے۔ یہ روش منٹو کی تخلیقی انانیت اور اس کے فنی کمال سے ہم آہنگ نہیں کہی جا سکتی۔ محققہ معلومات کے مطابق، منٹو نے اپنی محدود مختصر تخلیقی زندگی میں کل دو سو اڑتیس افسانے لکھے جن میں سے تین تا حال لاپتہ ہیں، پینسٹھ ڈرامے لکھے اور چوبیس خاکے، جن میں سے ایک غائب ہے (اس اطلاع کے لئے میں پروفیسر شمس الحق عثمانی کا شکرگزار ہوں۔ ) ان میں اعلی درجے کی تخلیقات کا تناسب زیادہ نہیں ہے۔ لیکن منٹو کی منتخب تحریروں میں ایک عجیب و غریب بے ساختگی ہے جیسے وہ بغیر کسی بیرونی کاوش کے بس اپنے آپ پھوٹ پڑی ہوں، سبز شاخ پر نئی کونپلوں کی طر ح۔ ہمارے فکشن کی روایت کو منٹو سے زیادہ فطری، بے دریغ اور ایک انوکھی اندرونی، ناقابل فہم طاقت سے مالا مال افسانہ نگا ر نہیں ملا۔اسی لئے، منٹو کے افسانوں کی تاریخیت، سماجی معنویت اور معاشرتی سیاق پر ضرورت سے زیادہ اصرار اور یکسر غیر تخلیقی سطح پر منٹو کی تعبیر کے عمل سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ منٹو کی اصل ہنر مندی تو اس کی سادہ کاری، اس کے برتاؤ اور اس کے طرز اظہار میں ہے۔ تاریخ اور سیاست کی وضع کردہ سچائیوں کو وہ اپنے شعور کی راہ سے پرے ڈھکیل کر کس طرح ایک نئی اور دائمی سچائی میں منتقل کرتا ہے، انسانی تجربے کی آنی جانی، اور فانی صورتوں کو کیوں کر ہمیشگی اور دوام و استحکام کے راستے پر لے جاتا ہے، اس عمل میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے معاصرین میں یہ ہنر اور سلیقہ منٹو کے بعد، سب سے زیادہ شاید غلام عباس کے حصہ میں آیا تھا، ورنہ تو اپنی بصیرت اور حسیت کے نازک ترین ارتعاشات کے باوجود نہ تو بیدی اس درجہ کمال تک پہنچ سکے اور نہ ہی اپنی تمام تر درد مندی کے باوجود کرشن چندر اس حیران کن حد امتیاز کو عبور کر سکے۔’ہتک‘، ’بابو گوپی ناتھ‘، ’کالی شلوار‘، ’موذیل‘، دھواں‘، ’گورمکھ سنگھ کی وصیت‘، ٹیٹوال کا کتا‘، ’ٹوبہ ٹیک سنگھ‘ ، ’رام کھلاون‘ اور ’کھول دو‘ جیسے افسانے صرف کھلی آنکھوں کی گرفت میں آنے والے مظاہر نہیں ہیں۔ یہ صرف مثالیں ہیں، منٹو کے شاہ کار افسانوں کی فہرست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی اہم ہے کہ زمان ومکاں کے ایک ہی دائرے میں قصہ گوئی کی فطری اور بے تصنع صلاحیت سے مالا مال لکھنے والوں کا ایسا اجتماع پھر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ منٹو، عصمت، غلام عباس، حیات اللہ انصاری، عسکری اپنے شخصی امتیازات کے ساتھ کم و بیش ایک ہی دور کے لکھنے والے تھے۔ ان میں منٹو نے اپنے بعد کے کچھ لکھنے والوں کے لئے جو ایک ماڈل کی شکل اختیار کر لی تو اس کا کچھ سبب منٹو کی افسانوی شخصیت بھی تھی۔ شخصیت کے اسی عنصر نے منٹو کی جبلی خود سری، سنسنی خیزی اور انانیت کو بھی اساس مہیا کی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی غور طلب ہے کہ منٹو کی تقلید میں پرجوش لکھنے والوں کی اکثریت، دوسرے اور تیسرے درجے یا مقبول عام (popular) لکھنے والوں پر مشتمل تھی۔منٹو کے پاس اپنی ہر کمزوری اور کجی کا جواز تھا۔ اس کے بیشتر نقادوں نے اسے اس کی اپنی قائم کردہ منطق کے رو سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لئے، منٹو کے افسانوں میں ہم وہی کچھ ڈھونڈتے اور دیکھتے ہیں جو منٹو کی اپنی تلاش کا حاصل تھا۔ ہمارا ذہن اکثر اس طرف نہیں جاتا کہ منٹو کے عہد کی دنیا میں بہت کچھ اور بھی تھا، جس کو دیکھنے اور سمجھنے کی مہلت منٹو کو نہ تو اس کی زندگی نے دی، نہ زمانے نے، اور اب تو منٹو کے کچھ نقاد اس کے درپے ہیں کہ منٹو کی دنیا کو اور زیادہ سمیٹ دیں۔ اس کی سب سے ضعیف البنیاد مثال منٹو پر فتح محمد ملک کی کتاب ہے۔ یعنی کہ ہم منٹو سے اس کی وہ خوبی بھی چھین لینا چاہتے ہیں جسے تقسیم اور فسادات کے ماحول نے ایک جرأت مندانہ اور غیر معمولی انسانی بنیاد فراہم کی تھی۔ ہر چند کہ پہلی جنگ عظیم کے پیدا کردہ ماحول میں مغرب نے جس پایے کا ادب تخلیق کیا تھا، اس کے مقابلے میں ہمارا تقسیم کا نمائندہ ادب کمتر درجے کا ہے، تاہم منٹو نے اس سانحے کو تخلیقی معروضیت اور آزادانہ شعور کے جس زاویے سے دیکھا تھا، اس تک، ایک بیدی کو چھوڑ کر منٹو کے کسی اور ہم عصر کی رسائی نہ ہو سکی۔یہا ں معروضیت کا مطلب عقلیت پسندی ہرگز نہیں ہے۔ تخلیقی آدمی کے لئے تعقل کی راہ میں ہزار خطرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ عقلیت ایک خطرناک اسلحہ ہے۔ کبھی کبھی یہ اس شخص کا کام بھی تمام کر دیتی ہے جو اسے کام میں لانا چاہتا ہے۔ یہ جتنا کچھ دیتی ہے اس سے زیادہ چھین لیتی ہے۔ اسی لئے اپنے بعض معروف ترقی پسند معاصرین کے برعکس، منٹو نے عقلیت پسندی کے نقصان کو تو سمجھ ہی لیا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فنکارانہ اور تخلیقی بصیرت پر یہ رمز بھی روشن ہو گیا تھا کہ آئڈیا لاگ ہونے کا مطلب، اپنے تخیل کی موت کو قبول کر لینا ہے۔ اس طرح کی شکست فن کار منٹو کی انا پروری سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اظہار و بیان کی سطح پر منٹو نے تجربہ پسندی کا راستہ بھی اپنے لئے کھلا رکھا۔ یوں بھی عام اردو فکشن کی رفتار کے مقابلے میں ہماری زندگی اور وقت کی رفتار تیز تر تھی۔ منٹو نے ’باردۂ شمالی‘ (اشاعت ۱۹۵۵)، ’پھندنے‘ (اشاعت۱۹۵۵) اور ’کالی کلی‘ (اشاعت نومبر ۱۹۶۰، نقوش، لاہو ر) جیسے کچھ افسانے، جو لکھے تو شاید صرف تفریح طبع کی خاطر یا خود کو آزمانے کے لئے، اس لئے ہرگز نہیں کہ دوڑتی بھاگتی زندگی کے تغیرات کا ساتھ دیا جائے اور شخصی و اجتماعی زندگی کے تجربوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ایک نئی لسانی تشکیل کے واسطے سے گرفت میں لیا جا سکے۔ افتخار جالب اور انیس ناگی کی موشگافیوں اور باریک بینی کے باوجود، منٹو کا یہ تجربہ، تجربہ ہی رہا، اردو افسانے کی روایت میں کسی نئے موڑ، کسی سنگ میل کی حیثیت اسے نہیں مل سکی۔ انور سجاد کا بیان ہے کہ انہوں نے افسانہ لکھنا ’پھندنے‘ سے سیکھا (شعور، چار، دہلی) لیکن اس سطح پر منٹو کی تقلید کا رنگ ان کے یہاں زیادہ واضح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں، یہ واقعہ بھی غور طلب ہے کہ منٹو کو اپنے احساسات پر وارد ہونے والے کسی بھی تجربے کے بیان میں اخفائے حال کی حاجت نہیں تھی۔ وہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے گھبراتا نہیں تھا کہ خود اس کے اپنے وجود کی زہرنا کی نے اسے تخلیقی ادراک و اظہار کی سطح پر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کی راہ دکھائی تھی۔یوں بھی منٹو کے شعور کی تربیت میں جن اشخاص، رویوں اور فکشن کی روایت کے جن وسائل کا رول رہا تھا، ان میں کہیں بھی انسان کو تجرید یا علامت کے طور پر دیکھنے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ انیس ناگی کا یہ قول کہ ’’منٹو نے تاثراتی اور ریئلسٹک اسلوب میں جنسی محرومی اور معاشرتی خوف کو ’پھند نے‘ کے حوالے سے نمایاں کیا ہے، اور یہ کہ اس نوع کے افسانے ’’اردو کے نئے افسانہ نویسوں کے لئے ایک اعلیٰ مہارت کی مثال‘‘ ہیں، شاید منٹو کی ایک وقتی تحریک اور محض تجربہ پسندی کے شوق کی ایک لہر سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ اردو کے نئے افسانہ نگاروں میں علامت اور تجرید سے شغف نے جو بے ہنگم شور برپا کیا، وہ اب مدرسانہ اور مکتبی تحقیق و تفہیم کا موضوع بھی نہیں ہے۔ شمس الرحمان فاروقی کے لفظوں میں ’’نئے افسانے کے معمار اعظم‘‘ انور سجاد سے لے کر سمیع آہوجہ اور جدید تر نسل کی ذریات تک، کہیں بھی علامت اور تجرید کا یہ آئین اپنے قدم جما نہ سکا۔ بہ قول انتظار حسین، اس نوع کے نئے لکھنے والے بہت جلد پچک گئے۔ انور سجاد نے بے شک کچھ غیر معمولی افسانے لکھے مگر وہ جلد ہی تھک کر بیٹھ رہے۔ تجربہ وہی اچھا جو سانس لینے کی طرح فطری بن جائے۔کہیں ایسا تو نہیں کہ منٹو کے عہد نے حقیقت پسند افسانے اور نیچرل ازم کا جو معیار قائم کیا تھا، اس سے علامتی اور تجریدی افسانے کا تصادم اصلاً ایک مفروضہ تھا۔ یا یہ سارا تصادم صرف مصنوعی اور خیالی یا fake تھا۔ افسانہ یا تو افسانہ ہوگا یا افسانہ ہوگا ہی نہیں۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ بیسویں صدی کی چھٹی دہائی کے دوران، ترقی پسند تحریک پر طاری ہونے والے اضمحلال کے ساتھ، جدیدیت کے میلان کی نمائندگی کا اعلان کرنے والے کچھ افسانہ نگاروں نے ’’کہانی کی کی موت‘‘ کا جو منشور عام کیا، اس کے پس منظر میں تاریخ کی موت، عقیدے کی موت، آئڈیا لوجی کی موت اور شاعری کی موت یہاں تک کہ انسان کی موت کے اعلانات کی گونج بھی تھی۔ کچھ نئے افسانہ نگاروں نے اس مرگ مسلسل کی توسیع کے عمل میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے افسانے کو بھی شامل کر لیا تھا۔ ایک مفروضہ یہ بھی سامنے آیا کہ اب شاعری اور افسانے کے بیچ کی لکیر غائب ہو چکی ہے اور نیا افسانہ ایک نئی تعریف کا طلب گار ہے، جو نثر اور نظم کی روایتی تقسیم کو مٹادے، اسی طرح جیسے نئے معاشرے کے تنہا فرد نے جیتے جاگتے کردار اور اس کی تجرید یا ہیرو اور اینٹی ہیرو کا امتیاز ختم کر دیا ہے۔ظاہر ہے کہ یہ روش نئے افسانے کو راس نہیں آئی کہ اس کے نتیجے میں افسانے کا قاری غائب ہوتا جا رہا تھا، اور افسانہ نیا ہو یا پرانا، اس کی بقا کی ضمانت یا اس کی survival kit اس کا قاری ہے۔ افسانہ تو افسانہ، ایسی شاعری بھی جو اپنے قاری کے سامنے ایک بے مزہ معمے یا puzzle کے طور پر نازل ہو اور نسخہ ترکیب استعمال کے بغیر کسی کام کی نہ ہو، زیادہ دنوں تک نہیں چلتی۔ اس کا وجود عدم برابر ہے۔اگست ۱۹۷۱ میں علی گڑھ مسلم یونیورسیٹی کے شعبہ اردو نے اردو فکشن پر ایک سہ روزہ سیمنار کا انعقاد کیا تھا۔ اردو کے کئی نامور نئے افسانہ نگار شاید پہلی مرتبہ ایک ضابطہ بند مذاکرے کے لئے یکجا ہوئے تھے۔ اس موقع پر کچھ ایسے پرچے بھی پڑھے گئے جن کی معنویت تاحال باقی ہے۔ مثلاً، سریندر پرکاش نے اپنے مقالے میں کہا تھا، ’’جدید افسانے کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ افسانہ نگار کچے پکے تجربات، اس کے تعصبات اور اس کے complexes کو پڑھنے والے پر ٹھونسے، بلکہ میں ادب کو اپنی ذات کے اظہار کا ذریعہ نہیں سمجھتا، Self-explorationکا ذریعہ سمجھتا ہوں اور اس کے تجربے میں اپنے قاری کو participate کرنے کے لئے اکساتا ہوں، تاکہ جو نتیجے برآمد ہوں ان کا ایک سا تجربہ دونوں کو میسر ہو۔ میں ادیب کی حیثیت ایک عام آدمی کی سی مانتا ہوں، اسے پیغمبر بنانے کے رویّے پر معترض ہوں۔‘‘ (اردو فکشن، مرتبہ آل احمد سرور، اشاعت ۱۹۷۳، ص۳۶۳)ہمارے ریڈیکل افسانہ نگار بلراج مین رانے بہت دو ٹوک لہجے میں یہ خیال پیش کیا ہے کہ، ’’جدیدیت کا آغاز چند ایک حساس، دکھی اور برہم نوجوانوں کی تحریک تھی۔ ان چند لکھنے والوں کی برہمی جو غلط یا صحیح تو ہو سکتی ہے، سچی تھی۔ اس لئے نئی تحریرکا مشکل اور خطرناک کام ہوتا رہا ہے۔ آخر کار وہی ہوا جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوا تھا۔ مفاد پرست آئے قریب آئے، گھل مل بیٹھے اور جلد ہی وہ وقت آ گیا جب نئی نسل کی برہمی کا اظہار جو ایک مثبت قدر ہے، ایک بے ہنگم، بے رخ منشور میں گم ہو گیا۔‘‘ (حوالہ ایضاً۔ ص ۴۱۳)یاد کیجئے کہ ’کچھوے‘ (اشاعت ۱۹۸۱) میں انتظار حسین نے ’’نئے افسانہ نگار کے نام‘‘ جو کھلا خط شامل کیا تھا، اس کا خطاب بلراج مین را سے ہی تھا۔ انتظار صاحب نے لکھا تھا، ’’میر ے عزیز! میرے حریف! نئے افسانہ نگار بلراج مین را! نیا افسانہ تمہیں مبارک ہو۔ مگر مباش منکر غالب کہ در زمانہ تست۔ تم نے باقر مہدی کو بیچ میں ڈال کر مجھ سے جواب طلبی کی ہے۔ تمہارے بیان کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ انتظار حسین کی داستان یا کتھا علامتی اور تجریدی افسانے کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے۔، ابھی میں نے ان کے رسالے میں ان کا مضمون پڑھا ہے جس میں انہوں نے اپنا بیان دوہرایا اور لکھا ہے، نئے افسانے کا مقابلہ ترقی پسند افسانے سے نہیں، بلکہ داستانوی کہا نی سے ہے جس کے نمائندے انتظار حسین ہیں۔‘‘ انتظار صاحب مزید لکھتے ہیں، ’’اے نئے افسانہ نگار، اے مرے عزیز! مجھے پتہ ہے کہ نئے افسانہ نگار کے حصے میں بھی کچھ اذیتیں آئی ہیں۔ ایسانہ ہوتا تو نیا افسانہ کیسے وجود میں آتا، اردو افسانہ وہی ۳۶، والی لکیر کا فقیر بنا رہتا۔ اب بھی کتنے ہیں جو اس لکیر کو پیٹے جا رہے ہیں، حالانکہ سانپ نکل چکا ہے، مگر جو چھوٹی سی اذیت اس فقیر کے نصیب میں لکھی گئی ہے، وہ تمہیں عطانہیں ہوئی، یعنی نہ مین را کو، نہ سریندر پرکاش کو، نہ اپنے پاکستان کے انور سجاد کو، بس اس اذیت نے مجھے کام کا آدمی نہیں رہنے دیا، ورنہ میں بھی افسانے کی نئی تکنیکیں سیکھ کر نیا افسانہ نگار بننے کی کوشش کرتا۔‘‘یہ ایک دل چسپ تحریر ہے جس میں نئے پرانے افسانے کے مضمرات پر انتظار صاحب نے اپنے مخصوص پیچ دار انداز میں کئی معنی خیز اور بحث طلب باتیں کہی ہیں۔ یہاں ان سب کا احاطہ تو ممکن نہیں، پھر بھی زیر گفتگو موضوع اور مسئلے کے پیش نظر اس تحریر کا ایک اور اقتباس دوہرانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں، ’’اس بر صغیر کے ہزاروں برسوں میں سے مختلف کل میرے تصور میں رچنے لگے اور بھی کل ہوں گے جو میرے اندر ہیں مگر مجھے ان کا شعور نہیں۔ سب دن اور سب زمانے ہمارے اندر ہیں مگر ہم اپنی تنگ ظرفی سے انہیں مار کر ماضی بنا دیتے ہیں اور اپنے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک بڑا مدفن ہے جس میں جانے کتنے آج، کل بن کر دبے پڑے ہیں۔ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ الف لیلہ، آگ کا دریا اور کتھا سرت ساگر تینوں میرے ہی زمانے کی کتابیں ہیں، سوجیسے میرا ہم عصر بلراج مین را، ویسے میرے ہم عصر سوم دیو جی۔ سو میرے بھائی! یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہاری خاطر اور تمہارے تنک سے آج کی خاطر سوم دیو جی کی ہم عصری سے انکار کر دوں۔ آگے تم سوچو!‘‘ (حوالہ ایضاً، ص۷۳۸)یہاں سامنے کی بات سریّت اور مابعد الطبیعات کے حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی معنویت ہے اور ہر لکھنے والے کے حساب سے اس کا اپنا تناظر۔ اس کی تفصیل میں موضوع سے ہٹ کر بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے سردست میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہو ں کہ نیا افسانہ تاریخ کے خلاف نہیں، تاریخ کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کے خلاف ہے۔ ہمار ایک ماضی وہ بھی تو ہے جو محض آرکائیوز کی ملکیت نہیں بن سکا ہے اور صدیوں کی اوبڑ کھابڑ سطح کو پار کرتا ہوا، ہمارے آج یعنی حال کے منطقے میں داخل ہو گیا ہے اور انتظار حسین سمیت بہت سے نئے لکھنے والوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔اس اقتباس میں انتظار صاحب کا اشارہ جس ماضی کی طرف ہے، وہ ایک لحاظ سے تخلیقی سطح پر از سر نو وضع کردہ ماضی ہے اور نئے افسانہ نگار کے ادراک اور سر رشتہ ایجاد کی دریافت اس رویّے نے نئے افسانے میں بے شک ایک نئی جہت کا اضافہ تو کیا ہے مگر اصل مسئلے سے ہمیں دور بھی کر دیا ہے۔ بہر نوع یہاں اپنے وقت اور اس گفتگو کے حدود کی وجہ سے اس مسئلے میں الجھنے کی بجائے میں آصف فرخی کے ان چند جملوں پر یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ، ’’افسانے کا نقاد اگر خود بھی افسانہ نگار ہو تو اس کے ساتھ یہ مشکل درپیش آتی ہے کہ وہ شعور ی طور پر اپنے افسانوی عمل یا ترجیحات کی تاویلیں پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خیر، یہ کوئی شرعی عیب بھی نہیں، اس لئے کہ انتظار حسین کی تنقید میں شدت اور چمک آتی ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے ایسے کسی تعصب کا جواز پیش کر رہے ہیں ہوں جو ان کے افسانوی عمل سے پھوٹا ہو۔‘‘ (مقدمہ۔ افسانے کی تلاش، نیر مسعود، اشاعت ۲۰۱۱، ص ۸)مگر انتظار حسین نے ایسے افسانے بھی تواتر کے ساتھ لکھے ہیں جن کی جڑیں ہمارے اور خود انتظار حسین کے مخصوص حال میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے واسطے سے جس سچائی کا ظہور ہوا ہے وہ ’’آج‘‘ کے ادیب، آرٹ، عوامی ذرائع ابلاغ کی مشترکہ ملکیت اور پہچان ہے۔ یہ ملکیت اور پہچان ہے کیا؟ تخلیقی اضطراب، اداسی، برہمی کے وہ عناصر جو اس عہد کے شعور کو موجودہ سیاسی کلچر، اقتدار کے عدم توازن، صارفیت، ہائپر ٹکنالوجی، مذہبی نیز نظریاتی شدت پسندی اور فضائی آلودگی کی دین ہے۔ فطری زندگی کے جو ہر، سیاست اور اخلاق یا ادب اور اجتماعی اقدار کے تصور سے دوری نے ہماری دنیا اور زمانے کے لئے جن خطروں کو جنم دیا ہے، ان کو سمجھنے سمجھانے کی ذمہ داری جدید سائنس اور ٹکنا لوجی سے زیادہ سماجی اور انسانی علوم کے ترجمانوں پر آپڑی ہے۔ ہمارے عہد کا ادب اور آرٹ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ادیب ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور اور بے بسی کے احساس میں مبتلا فرد سہی، مگر اس ذمہ داری کا بوجھ بساط بھر اس نے بھی اٹھا رکھا ہے۔ وہ اپنے عہد کا ضمیر بھی ہے۔ نیر مسعود کے لفظوں میں،’’اس معاملے میں افسانہ ذرائع ابلاغ کا مقابلہ نہیں کرسکتا لیکن اس نے مثال کے طور پر فساد اور تشدد کے موضوع کو ترک نہیں کر دیا ہے، البتہ افسانہ نگار اس قسم کے واقعات کے تفصیلات بیان کرنے اور ان کی کیمرائی تصویریں دکھانے کے بجائے یہ دکھانے پر زور دیتا ہے کہ یہ خارجی صورت حال فرد کے باطن میں اتر کر کیا اثر کر رہی ہے۔‘‘ (افسانے کی تلاش، ص ۶۲)اپنے زمان و مکاں، اپنے سامنے کی بنتی، بدلتی، بگڑتی اور بکھرتی ہوئی تاریخ کا گواہ شاعری سے زیادہ، آج کا افسانہ ہے۔ ہونا بھی یہی چاہئے تھا، کیونکہ افسانہ بہرحال، اسی پریشان فکر اور اپنے حال سے پشیمان زمین کی آواز ہے، نوائے سروش نہیں ہے۔ اس کے ساتوں سرخود اس کو اساس مہیا کرنے والی زندگی کے ساز سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ افسانہ نگار کے لئے لکھنے سے پہلے اپنے زمان ومکاں کی بابت سوچنے، اشیا اور مظاہر کو سمجھنے، پھر افسانے کو تلاش کرنے، دریافت کرنے، بیان کرنے کی منزل آتی ہے۔لہٰذا ایسے وقت میں جب لکھنے والے کا تجربہ منٹو اور اس کے ہم عصر ہی نہیں، بعد کے افسانہ نگاروں، انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، اکرام اللہ، عبداللہ حسین، محمد سلیم الرحمان، ضمیر الدین احمد، مسعود اشعر، حسن منظر، خالدہ حسین اور انور سجاد سے لے کر اسد محمد خاں اور نیر مسعود کی کہانیوں کے سامنے آنے کے باوجود پہلے سے محدود تر ہوتا جا رہا ہو، اور اس کے سرو کار سمٹتے جا رہے ہوں، تو اس کی مشکل اور بڑھ جاتی ہپے۔ میڈیا (الیکٹرانک اور پرنٹ دونوں ) کی دراز دستی اور سیاست کی گرم بازاری اور تشدد کی نت نئی شکلوں اور اخلاق و اقدار کے تئیں روز افزوں بے حسی اور بے بسی نے نئے افسانہ نگار کے سامنے ایک وسیع اور رنگار رنگ فکر ی منظر نامہ بچھا دیا ہے۔ فلسفہ، نفسیات اور سماجی علوم کے فراہم کردہ اس منظر نامے کی تعبیر اور عکاسی کے عمل میں کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی سطح پر نیا افسانہ نگار بھی شریک ہے۔ یہ جیتے جاگتے تجربے کا بدل تو نہیں مگر انسانی زندگی، وجود اور اس کے آشوب کی تخلیقی تعبیر کا ایک مؤثر وسیلہ ضرور ہے۔افسانے اور افسانہ نگار کے رول کا انحصار کبھی بھی صرف سنسنی خیزی پر یا کرتب بازی پر یا عام قاری کی دل چسپی کا سامان پیدا کرنے پر نہیں رہا اور اب تو فکشن کے دوش بدوش انہونے واقعات اور جرائم کی رپورٹنگ سے بھرے ہوئے اخباروں اور نیوز چینلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے pop-Fiction کی ایک شکل بھی ہے۔ اس صورت حال نے نئے افسانہ نگار کے لئے مزید دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ اپنے افسانے کا بیج اسے حافظے کی زمین سے پھوٹتا ہوا شاید اب بہ مشکل ہی دکھائی دیتا ہے۔ اپنی صورت حال کے سیاق میں خواہ مسعود اشعر ’’اپنے گھر‘‘ کا حال لکھ رہے ہوں یا آصف فرخی ’’شہر بیتی‘‘ کا بیان کر رہے ہوں، آج کا رشتہ گزرتے ہوئے کل کے بجائے آنے والے کل سے قائم ہو جاتا ہے۔یہ لے انتظار حسین کے حالیہ افسانوں اور دوسری تحریروں میں بھی تیز تر ہو گئی ہے۔ مزاحم کے ایک خاص رویّے اور مستقبلیت (فیوچرازم) کی ایک لہر نے، اسی لئے، نئے افسانے کے ایک ناگزیر عنصر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ خالد جاوید، صدیق عالم، سید محمد اشرف کے افسانوں میں کھلا سیاسی موقف اپنائے بغیر، اس عنصر نے ایک خاص مفہوم اپنایا ہے۔ اتفاق سے یہ تینوں افسانہ نگار ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ مگر ان کے معروف ہم عصر، ایک اور ہندوستاتی افسانہ نگار، مشرف عالم ذوقی نے نئے افسانے کی غیر منقسم روایت کے حساب سے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ،’’فکشن کے نئے دستخط ادب میں ناپید ہیں۔ پرانے دستخط اور کم و بیش جنہیں آج بھی نوجوان قلم کار کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ پچاس نہیں بلکہ ساٹھ سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں۔ تادم تحریر میں خود بھی عمر کی بیالیس بہاروں اور بیالیس خزاؤں کا حساب لے چکا ہوں اور آپ جانئے کہ منٹو تو اس عمر میں اپنے شاہ کار چھوڑ کر رخصتی کا پروانہ بھی لے کر آ گیا تھا۔ اردو ادب میں اس سے زیا دہ تاریکی کا اس کے قبل کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔‘‘ (سہ ماہی آئندہ، کراچی، شمار ہ ۳۶؍۳۵، اکتوبر تادسمبر ۲۰۰۴)’’نئے افسانے کے قاری اور اس کے معمار، دونوں کو کبھی دیانت داری کے ساتھ اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہئے کہ اس خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ محمود ایاز نے اپنے رسالے ’سوغات‘ میں تخلیقی استعداد کی اس قحط سالی سے تنگ آکر کہہ دیا تھا کہ ایسے لوگ جو لکھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، انہیں کچھ اور کرنا چاہئے۔ خیر یہ تو ایک تربیت یافتہ قاری کا تاثر تھا اور یہ مشورہ ایسوں کے لئے تھا جو لکھنے کے عمل کو کاغذ سیاہ کرنے سے زیادہ ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کے طور پر دیکھتے ہوں۔‘‘ مگر اب ذرا یہ بھی دیکھئے کہ ایک باکمال افسانہ نگار کا موقف اس معاملے میں کیاہے، ’’اچھے افسانے آج بھی اچھی تعداد میں لکھے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تو صورت حال اطمینان بخش ہے لیکن اچھے افسانوں کے مقابلے میں برے افسانوں کا تناسب آج جتنا زیادہ ہے اتنا پہلے نہیں تھا اور برے افسانے بھی آج جتنے برے لکھے جارہے ہیں اتنے برے کبھی نہیں لکھے گئے اور یہ بات اطمینا ن میں خلل پیدا کرتی ہے۔‘‘ (نیر مسعود، آج کا افسانہ اور افسانے کا مستقبل کیا ہے؟ افسانے کی تلاش، ص ۴۴)رات سے کہانی کے تعلق کی روایت پرانی ہے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ اندھیر ے کی اس فضا میں جہاں تہاں روشنی کے کچھ چھینٹے ہمیں زیادہ دور تک تو نہیں لے جاسکتے۔ یوں بھی اندھیرا طر ح طرح کے وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ سو اس خستہ حالی سے نجات کی صورت کیا ہوگی، سوائے اس کے کہ نیا افسانہ نگار اپنے آپ سے الجھتے رہنے کے علاوہ پیچھے مڑکر اردو افسانے کی روایت کے کچھ سبق بھی دوہرا لیا کرے۔ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ پہنچے ؟ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت آج شاید پہلے سے زیادہ ہے۔کلیدی خطبہ منٹو سیمنار (نیا اردو افسانہ)، لمز، لاہور، اپریل ۲۰۱۲