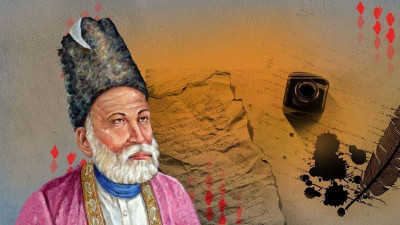انتظار حسین ایک ادھوری تصویر
ایک نئے افسانہ نگار نے برسوں پہلے مجھے لکھا تھا، ’’ہماری کہانیاں آپ کو اس وقت تک پسندنہیں آئیں گی جب تک کہ آپ قرۃ العینوں اور انتظار حسینوں کے سحر سے نکل نہ آئیں۔‘‘ پتہ نہیں یہ بات کتنی سچ ہے، لیکن ہو نہ ہو ہر پڑھنے والے کے احساسات اپنے گرد کچھ دائرے ضرور بنا لیتے ہیں۔ میں ان دائروں پر اپنی موجودہ صورت حال کے حساب سے نظر ڈالتا ہوں تو اور بھی کئی نام ابھرتے ہیں۔ نیر مسعود، اسد محمد خاں، محمد خالد اختر، حسن منظر، اکرام اللہ، سریندر پرکاش، محمد سلیم الرحمن۔ ظاہر ہے کہ یہ فہرست ادھوری ہے اور اس میں گاہے ماہے نئی کہانیوں اور نئے چہروں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ فہرست گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن تو یہ ایک الگ بحث ہے۔
سردست تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اور آرٹ کی دنیا سے ہمارے رابطوں میں نئے پرانے کی تفریق سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی جانے انجانے میں اچانک صدیوں پرانے اور دھندلے لفظ اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور ہمارے حاضر کے شعور میں اپنے لئے جگہ بنانے لگتے ہیں۔ پھر انتظار حسین کے ساتھ تو معاملہ شروع ہی سے مختلف تھا۔ ’’گلی کوچے‘‘ اور ’’کنکری‘‘ کی کہانیاں میں نے کالج کے دنو ں میں پڑھیں، جب نئے ادب سے شغف کی بنیادیں خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھیں اور ’آخری آدمی‘ (اشاعت ۱۹۶۷ء) تک پہنچتے پہنچتے تو کچھ اس طرح کا تاثر پیدا ہوا کہ یہ تو ایک نئی کتاب ہی نہیں، ایک نیا تجربہ بھی ہے۔
ان دنوں میں اندور میں تھا جہاں سید وقار حسین (سابق صدر اور پروفیسر شعبہ انگریزی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) کی مستقل رفاقت حاصل تھی۔ ہم دونوں یہ کہانیاں کبھی کبھی ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے۔ پھر رات گئے ان کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں۔ انتظار حسین سے ملاقات اس کے کئی برسوں بعد (۱۹۶۷ء میں) ہوئی اور پل بھر کے لئے یہ خیال نہیں آیا کہ ہم پہلی بار ملے ہیں۔ ملاقات نئی سہی، لیکن انتظار حسین کی بصیرت سے رشتہ پرانا ہو چکا تھا۔ اس وقت تک انتظار حسین کی تحریریں بغیرکسی شور شرابے کے ہمارے اپنے وجدان کا حصہ بن چکی تھیں۔ شاید دنیا کے سب سے زیادہ مانوس اور ممتاز ادب پاروں میں اکثریت ایسی ہی تحریروں کی ہوتی ہے جو بغیر کسی ظاہری کوشش کے ہم سے قربت حاصل کر لیتی ہیں اور بادی النظر میں اتنی دھیمی، رواں دواں اور سہل نظرآتی ہیں جیسے کسی ٹہنی پرنئے انکھوے پھوٹ رہے ہوں۔
ادب کی تخلیق کے عمل کو ورزش سے الگ ہوناچاہئے۔ بناوٹ اور پوز آدمی میں ہو یا قصہ کہانی اور شعر میں، ا س کے ساتھ دور تک چلنا میرے لئے دوبھر ہو جاتا ہے۔ انتظار حسین کی شخصیت بھی، ان کی کہانیوں کی طرح بہت سادہ اور عام دکھائی دیتی ہے۔ نہ کوئی تام جھام، نہ کسی طرح کا طمطراق۔ لفاظی، عبارت آرائی، خطابت، بلند آہنگی، سجاوٹ کے عناصر سے ان کی شخصیت عاری ہے اور ان کی تحریر بھی۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹاف روم میں بہت عجلت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ایک جلسہ ہوا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے احساسات مرتب کئے اور اپنی بات اس موقع پر یہاں سے شروع کی کہ، ’’انتظار حسین میرے لئے نام نہیں، ایک تجربہ ہے۔ ایسا تجربہ جو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گئے دن یابیتے ہوئے لمحے کا واقعہ نہیں بن جاتا۔ اسے صرف اپنے وجود کے حوالے سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس تجربے کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی حدیں کیا ہیں؟ اس زندگی کو جو مجھے بسر کر رہی ہے اور اس زندگی کو جس کے تماشے میں اپنے آپ کو میں گھرا ہوا پاتا ہوں، اس تجربے نے کیوں اور کس طرح اور کن جہتوں سے متاثر کیا ہے، اس حقیقت کا غیر جذباتی اور معروضی تجزیہ میرے لئے ممکن نہیں۔ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ تجربہ میرے لئے اچھا ہے یا برا، مفید ہے یا مہلک! تخلیقی لفظ کامعاملہ ادب پڑھنے والوں کے لئے بہت ذاتی ہوتا ہے۔ بشرطیکہ پڑھنے والا ادب کو، ایک روحانی احتیاج کے طور پر پڑھے، صرف کسی ذہنی ضرورت یا تنقید نویسی کے لئے نہیں۔‘‘
ادب کے نام پر تھیوری کاپیشہ کرنے والے ادب یوں پڑھتے ہیں جیسے مانگے تانگے کے پرانے کوٹ پہن رہے ہوں یا اترنوں کے کاروبار میں مصروف ہوں۔ ایسے اصحاب کامسئلہ ادب نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ذات ہوتی ہے یا پھر عام زندگی کے مقاصد کی حصول یابی کے لئے ادب کو زینہ بنانے کی روش۔ مجھ میں اس ابتذال کو جھیلنے کی تاب نہیں! انتظار حسین کے ساتھ میرا قصہ ظاہر ہے کہ بہت مختلف ہے۔ میرے محترم دوست اور نامور نقاد فضیل جعفری صاحب نے، جن کی رایوں کی میرے دل میں بہت قدر ہے، انتظار حسین کے بارے میں میر ی ایک تحریر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو کچھ من شدم تومن شدی والا معاملہ ہے۔ بے شک بات یہی ہے اور صرف انتظارحسین نہیں، میں نے تو دنیا کے بہت سے لکھنے والوں کی تحریریں آپ بیتی ہی کی طرح پڑھی ہیں اور انتظار حسین کا قصہ اپنے حساب سے تو کچھ یوں بنتا ہے کہ اردو کے جن معدودے چند لکھنے والوں کی بصیرت میں مجھے اس عہد کے سوالوں اور خود اپنے روحانی مسئلوں کا سراغ ملتا ہے، ان میں بھی انتظار حسین کا نام بہت نمایاں ہے۔
اپنے افسانے کے حوالے سے انتظار حسین نے لکھا تھا، ’’افسانے میں میرا مسئلہ ظاہر ہونا نہیں ہے، روپوش ہونا ہے۔ پیغمبروں اور لکھنے والوں کا ایک معاملہ سدا سے مشترک چلا آتا ہے۔ پیغمبروں کا اپنی امت سے اور لکھنے والوں کا اپنے قارئین سے رشتہ دوستی کا بھی ہوتاہے اور دشمنی کا بھی۔ وہ ان کے درمیان بھی رہنا چاہتے ہیں اور ان کی دشمن نظروں سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ میرے قارئین میرے دشمن ہیں۔ میں ان کی آنکھوں، دانتوں پر چڑھنا نہیں چاہتا۔ سوجب افسانہ لکھنے بیٹھتا ہوں تواپنی ذات کے شہرسے ہجرت کرنے کی سوچتا ہوں۔ افسانے لکھنا میرے لئے اپنی ذات سے ہجرت کاعمل ہے!‘‘
انتظار حسین کے لئے اپنی ذات سے ہجرت کالمحہ شاید صبح سویرے کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب گردوپیش کی زندگی بھی آنکھیں ملتی ہوئی جاگ چکی ہوتی ہے اور پرندے اپنی نیند پوری کرکے اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ میں نے تو لاہور میں یادلی میں جب بھی انتظار حسین کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھا، اسی عالم میں دیکھا ہے۔ انتظار حسین کے دن دنیا کے جھمیلوں کے لئے، شامیں دوستوں کے لئے ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی صبحیں اپنی سہاونی فضا اور اپنے پرندوں کے چہچہے سمیت انتظار حسین کی اپنی ملکیت ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت مظاہر میں اور انتظار حسین میں ایک خاموش معاہدہ سا ہو جاتا ہے اوردونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ شہر لاہور کی جیل روڈ سے نکلتی ہوئی گلی میں انتظار حسین کا وسیع و عریض گھر، جس کے سبزہ زار میں ہارسنگھار، گڑہل اور لیمو کے پیڑ کھڑے ہیں اور جس کے پورٹیکو پر مدھومالتی کی ایک ہری بھر ی بیل کا سایہ ہے، وہاں بھی گھر کے اندرکی دنیا اور گھر سے باہر کی دنیا میں ایک اندرونی ربط کا بہانہ صبح کی اولین ساعتیں بنتی ہیں۔
میں نے اس عالم میں انتظار حسین کوجب بھی دیکھا، اپنے آپ میں گم کچھ سوچتے یا لکھتے ہوئے دیکھا۔ حد تویہ ہے کہ ناشتے کی میز پر بھی انتظار حسین کا دھیان اپنی پلیٹ کے ساتھ ساتھ کھڑکیوں سے جھانکتے ہوئے ان پرندوں پر ڈولتا رہتاہے جو ہر صبح انتظارحسین کے ناشتے میں شریک ہوتے ہیں۔ انتظار حسین ڈبل روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھری ایک پلیٹ، ایک پیالی میں پانی لے جاکے کھڑکی کی سل پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعدپ رندے اپنے ناشتے میں اور انتظار حسین اپنے ناشتے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کے لئے دن کے پھیلتے اجالے اور بڑھتی دھوپ میں گم ہو جانے کا مرحلہ آتا ہے۔
ایک صبح دلی میں ہم جامعہ نگر سے اوکھلا نہر اور جمنا جی کی طرف جانے والی سڑک پر چہل قدمی کے لئے نکلے اور ایک ہری بھری ڈالی پر فاختاؤں کی برات دکھائی دی تو انتظار حسین نے کہا، نئی شاعری میں اب فاختہ بولتی کیوں نہیں؟ یہ آواز ناصر کی غزل کے ساتھ رخصت ہوئی۔ وہ اس کے بولنے اور چپ رہنے دونوں کا نوٹس لیتا تھا!
فاختہ چپ ہے بڑی دیر سے کیوں؟
برصغیر کی تقسیم اور اپنی ہجرت کے واقعے سے شروع ہونے والی روداد ’’چراغوں کا دھواں‘‘ کااختتام انتظار حسین نے اس نوٹ پر کیا ہے کہ، ’’عید بقرعید پرجب میں نماز پڑھنے مسجد میں جاتاہوں توپہرے میں یہ فریضہ ادا کرتا ہوں۔ ہر برس پہرا پچھلے برس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔۔۔ مملکت اسلامیہ پاکستان میں اب سب زیادہ غیر محفوظ مقام مسجد ہے۔ کس پاکستان میں ہم نے صبح کی تھی۔ کس پاکستان میں اب شام کرتے ہیں۔ پھر بھی یاروں کی ہمت ہے کہ جوش و خروش سے اکیسویں صدی کے استقبال کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ جانے اکیسویں صدی ہمارے لئے کیا روکڑالے کر آرہی ہے، مگر عجب ہوا کہ ہم انتظار کر رہے تھے اکیسویں صدی کی سواری با دبہاری کا، مگر اس صدی کی سوار ی کے پہنچنے سے پہلے چودھویں صدی آن پہنچی اوراب مجھے اپنی نانی اماں یاد آ رہی ہیں۔۔۔
عجب بات ہے کہ میری نانی اماں نے چودھویں صدی کے بارے میں جو بتایا تھا وہی مہابھارت میں کل جگ کے ذیل میں بتایا گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ چودھویں صدی ہے یا کل جگ ہے۔ زمانہ بہرحال کالا پڑتا چلا جا رہا ہے اور سر پر ایک تلوا رلٹک رہی ہے بلکہ محاورے کو چھوڑو اور کہو کہ سروں پہ ایٹم بم گرج رہا ہے۔ جانے کب کس مورکھ کی کل اینٹھ جائے اور یہ دھم سے ہم پہ پھٹ پڑے۔ القارعۃ ماالقارعۃ اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ یہ دھماکہ ہے کیسا۔ تصور کرو اس دن کا جب آدمی ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے بکھرے پڑے ہوں اور پہاڑوں کی یہ صورت ہو جائے گی جیسے دھنکی ہوئی روئی۔ کم بخت زمانہ تو کالا پڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سفیدی تو بس اس مرغی کے انڈے جتنی باقی رہ گئی ہے۔۔۔‘‘
پہلی عالمی جنگ کے بعد یورپ میں دہشت اور فساد کی جو فضا پھیلی تھی، اس کے تذکرے میں لارنس نے لکھا تھا کہ درد، دہشت اور بربادی کے ایسے موسم میں چڑیاں چہچہانا بھول جاتی ہیں اور ہمارے نرم نازک جذبے رفتہ رفتہ رخصت ہونے لگتے ہیں۔ انتظار حسین کی تخلیقی شخصیت اور ان کے فکشن کی تشکیل کچھ ایسے ہی ماحول میں ہوئی ہے۔ یہ ماحول ایک دور رس خرابی اور انتشار کا ہے جب زندگی، زمانے اور انسانی کائنات، ان میں سے کسی کی وحدت باقی نہیں رہ جاتی۔ اشیا ٹوٹنے اور بکھرنے لگتی ہیں۔ آپسی رشتے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور فطرت سے، انسانوں سے، مظاہر سے ہماری دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اپنے آخری مجموعے ’’شہرزاد کے نام‘‘ میں میرے اور کہانی کے بیچ کے زیرعنوان انتظار حسین نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔
’’میں ان دنوں ’مشرق‘ میں کالم نگاری کرتا تھا۔ سیاسی مسائل سے منہ موڑ کربس لوگوں، درختوں، پرندوں کے چھوٹے موٹے معاملات پر لکھا کرتا تھا۔ سو اس شہادت پر بھی ایک کالم قلم بند کیا۔ پھر حلقہ ارباب ذوق کے جلسے میں جاکر دہائی دی۔ ان دنوں حلقے کے جلسوں میں رجعت پسند اور ترقی پسند دونوں قسم کے ادیب مل بیٹھ کر ادبی مسائل پر بحثیں کیا کرتے تھے۔ رجعت پسند ادیبوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک درخت کے کٹنے کو ایک انسانی واردات اور ایک ادبی مسئلہ بناکر کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ ادھر ترقی پسند دوستوں نے میری فریاد کو عین رجعت پسندی اور ترقی دشمنی قرار دیا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ پاکستان صنعتی عہد میں داخل ہو رہا ہے۔ سو درخت تو کٹیں گے، اس کے بغیر ملک ترقی کیسے کرےگا۔
بس پھر شہرمیں درخت اندھادھند کٹتے چلے گئے اور ایک روز مجھے ایک عجب فون آیا۔ بیگم حجاب امتیاز علی بول رہی تھیں، ’’انتظار صاحب! کیا آپ کو اس کاپتہ ہے کہ اب کے برس کوئل اس شہر میں خاموش ہے۔ جون شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی طرف سے کوئل کی کوک سنائی نہیں دیتی۔ اب بتائیے، آپ نے کوئل کی کوک سنی ہے۔‘‘ میں نے جناح باغ میں اپنی صبح کی سیروں کو یاد کیا اور حیران ہوا کہ کوئل کے کوکنے کا موسم توشروع ہوا ہے مگر ابھی تک قریب یادور سے اس کی کوک سنائی نہیں دی ہے۔ مگر مجھے اس کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا۔
’’آپ بجا فرماتی ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئل کی کوک نہیں سنی ہے۔‘‘
’’پھر آپ نے اس پرکالم کیوں نہیں لکھا۔ لوگوں کو اس واقعے کا علم ہونا چاہئے۔ انتظار صاحب لکھئے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ تو آپ لکھیں گے؟‘‘
’’جی لکھوں گا!‘‘
’’یہ واقعہ یقیناً ایسا تھا کہ اس پر لکھنا چاہئے تھا اور یہ واقعہ میری تو سمجھ میں آتا تھا۔ آخر درختوں کے قتل عام پر عالم فطرت کے کسی گوشے سے تو احتجاج ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں یہ احتجاج کوئلوں کی طرف سے ہوا اور اس طرح ہوا کہ انہوں نے چپ سادھ لی اورہمیں اپنی سریلی آواز سے محروم کر دیا۔۔۔‘‘
میرا خیال ہے کہ انتظار حسین کو سمجھنے کے لئے اس پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہ ظاہر ان کا اصرار اسی بات پر ہے کہ اپنے اور اپنی کہانی کے بیچ وہ کسی طرح کی غیر ضروری وابستگی کو حائل نہیں ہونے دیتے اور نہ تو خود کسی سیاسی، تہذیبی، معاشرتی نظریے کی پابندی قبول کرتے ہیں، نہ اپنے چاروں طرف رونما ہونے والے سیاسی واقعات کو خاطر میں لاتے ہیں۔۔۔ انتظار حسین بے شک بڑی سے بڑی واردات سے بھی اپنے احساسات کو پسپا نہیں ہونے دیتے۔ اپنا داخلی نظم اور توازن ہرحال میں بنائے رکھتے ہیں۔ کبھی اونچے سر میں اپنے ردعمل کا اظہار نہیں کرتے اور ایک اپنی بصیرت کے سوا، کسی نظریے، عقیدے، مکتب فکر، مصلحت اور جبر کو قبول نہیں کرتے۔ اسی لئے فطرت سے، کائنات سے، دنیا سے اور اپنے آپ سے ان کے رشتوں میں کسی طرح کا کھوٹ آنے نہیں پاتا۔ لیکن انتظار حسین کی کہانیوں میں ایک بات جو چھپائے نہیں چھپتی، ان کا اخلاقی ملال ہے اور اس ملال کے سلسلے بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔
’’ڈیڑھ بات اپنے افسانے پر‘‘ کرتے ہوئے انتظار حسین نے لکھا تھا، ’’لکھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹوکتا جاتا ہوں کہ نادان اسراف بے جا سے بازآ۔ دولت ہاتھ کامیل ہوتی ہے۔ لفظ ہاتھ کامیل نہیں ہیں۔ اتنے خرچ کرجتنوں کی ضرورت ہے۔۔۔ وہ زمانہ تو رہا نہیں جب مشرق والے مغرب کی ہر چیزکو آنکھیں بند کرکے قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب وہاں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں اپنی مشرقی روح کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میر ی ایک بغل میں الف لیلہ ہے اور دوسری بغل میں کتھا سرت ساگر ہے۔ افسانہ لکھوں یا ناول، مجھے اپنے فکشن کی ان دو بڑی طاقتوں کے سامنے جواب دینا ہے۔‘‘
یہ مشرقی روح صرف قصص اور داستانوں کے اسالیب سے عبارت نہیں ہے۔ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک زاویہ بھی ہے اور اس کا سیاق اتنا ہی وسیع و بسیط اور کثیرالجہات ہے جتنا ہماری تہذیب کا۔ اس معاملے میں انتظار حسین اردو کے تمام افسانہ نگاروں سے زیادہ حساس ہیں۔ اپنے تہذیبی اور فکری تشخص کو قائم رکھنے کے لئے انتظار حسین نے زبان وبیان، اپنے طرز احساس، اپنی فکر اور جذبے کے اظہار کی کچھ حدیں بنا رکھی ہیں۔ ان حدوں سے وہ کبھی باہر نہیں جاتے اوربہت سی بیرونی اور باطنی تبدیلیوں کے باوجود ان کا تخلیقی ادراک ایک خاص سطح کا پابند رہتاہے۔ شاید اسی لئے ان کے یہاں خیال اور بیان کے تکرار کی کچھ صورتیں بھی برابر سامنے آتی رہتی ہیں۔ تجربے اور ادراک کے حوالے بدل جائیں، جب بھی ایک تسلسل اور ایک رنگی کا احساس باقی رہتا ہے۔ اس ضمن میں ان کے اعترفی بیان ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا اقتباس ’کچھوے‘ کی اس عبارت سے ماخوذ ہے جو ’نئے افسانےنگار کے نام‘ انتظار حسین کے ایک خطاب کاحصہ ہے۔ کہتے ہیں،
’’جب میں ’کچھوے‘ لکھ رہا تھا تو مجھے خوب احساس تھا کہ میں اس سے پہلے ایک ’زرد کتا‘ لکھا چکا ہوں۔ تو پوچھوگے پھریہ کہانی کیوں لکھی۔ پتہ نہیں۔ شاید یہ وجہ ہو کہ مجھے یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کی بنیاد میں خرابی کامعاملہ نہیں ہے، بلکہ جس تہذیب کے سیاق و سباق میں یہ بات ہوئی ہے، اس تہذیب کی تعمیر میں خرابی کی کوئی صورت مضمر تھی کہ اس کے بطن سے ’زرد کتا‘ پیدا ہو گیا۔ اس تشویش میں سوچا چلو کسی دوسری تہذیب میں چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے تومیں پیچھے چلا اور یہ دیکھنا شروع کیاکہ جب میں بدھ دیوجی کے سنگھ میں تھا تو ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد میں کیا کررہاتھا۔ اگرخدا مجھے توفیق دے تو میں دوسری تہذیبوں میں لمبے سفرکروں اور دیکھوں کہ تہذیبیں بوریا سے قالین کا سفر کیسے طے کرتی ہیں؟ کب کس موڑپر ’زرد کتا‘ نمودار ہوتا ہے اورکیسے بلندیوں میں اڑتے اڑتے ڈنڈی دانتوں سے سرکنے لگتی ہے۔‘‘
دوسرا اقتباس ’شہرا فسوس‘ کے فلیپ پر منقول عبارت سے، ’’میں بھی اپنے وقت میں مقید ہوں اور اپنی واردات کا اسیر ہوں۔ میں کہانی کیا لکھتا ہوں اپنی بکھری مٹی سے ذرے چنتا ہوں، مگرمٹی بہت بکھر گئی ہے اور میں مجتہد نہیں، کہانی لکھنے والا ہوں۔ مٹی جمع کرنا اور کہانی لکھنا اب ایک لاحاصل عمل۔ بکھری مٹی سے ذر ے چننا اور کہانیاں لکھنا، جتنے ذرے چن سکتا ہوں انہیں غنیمت جانتا ہوں۔‘‘
اپنی زندگی سے اور اپنے زمان ومکاں سے وابستگی کی یہ شکل ایک تخلیقی مجبوری اور مقدر بھی ہو سکتی ہے۔ انتظار حسین نے اسے جو قبول کیا تو اس لئے کہ اس حصار کو توڑنا ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ گویا کہ بہ قول بیدل ’’زندگی در گردنم افگند‘‘ والا قصہ ہے۔ انتظار حسین یہاں بھی ادیب کی سماجی ذمہ داری اور منصب کے پھیرمیں پڑے بغیر اپنے زمانے اور اجتماعی زندگی کے حقوق ادا کرنے کے جتن کرتے ہیں، شادباید زیستن ناشادبایدزیستن۔
ایک سنجیدہ لکھنے والے کا احساس ذمہ داری ان کے شعور میں اسی طرح گھل مل گیا ہے جیسے ہوا میں خوشبو کی ایک لہر۔۔۔ ! اسی لئے انتظار حسین اپنے شعور کی کثیرالجہتی کا کبھی دعویٰ نہیں کرتے۔ مضامین میں ادبدا کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ان کے ادبی موقف کے بارے میں غلط فہمیاں عام ہوں۔ ریڈیکلزم اور ادب کے انقلابی رول کی ہنسی بھی اڑاتے ہیں۔ ترقی پسندوں سے ایک طرف، تجدد کے نام پر زبان وبیان اور ہیئت پرستی کی روش اپنانے والوں سے دوسری طرف، ان کی چھیڑ چھاڑ بھی جاری رہتی ہے۔۔۔ انہوں نے لکھا تھا، ’’بڑا ادب کسی بھی اقلیم میں درانہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس سیلاب پر کسی تکنیک کا بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تکنیک کا تنکا تو ادب میں ڈوبتوں کا سہارا ہے۔۔۔ افسانے کا ربط اجتماعی تہذیب اور اس کے سر چشموں سے ٹوٹ جائے تو وہ اپنی نئی تکنیکوں کے ساتھ نٹ کاتماشا ہوتا ہے یا پھر اشتہار ہوتا ہے۔۔۔‘‘
ترقی پسندوں نے ایک ضابطہ بند اقلیم سے رشتہ وفا استوار کرنے پر زور دیاتھا۔ نئے ادیبوں نے اپنی قوت ایجاد اور نئی تکنیک کے زعم میں (علامت، تجرید) افسانے کو جس حال تک پہنچایا وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ انتظار حسین رجعت پسند ہیں کہ ترقی پسند کہ جدید، یہ معمہ بہتوں کے لئے آج بھی حل طلب ہے۔ ایک چہرے میں اتنے چہرے ہیں کہ کثرت نظارہ سے انتظار حسین کے بہت سے نقاد پریشان ہو گئے۔ جذباتی انتہا پسندی کے ایک اس دور کو چھوڑ کر جو انتظار حسین کی تحریروں میں تقسیم کے بعد ہجرت کے تجربے کی کوفت سے پہلے پہل نمودار ہوا تھا، انتظار حسین کا تخلیقی تناظر، ان کے پہلے مجموعے ’گلی کوچے‘ (۱۹۵۲ء) سے تاحال ان کے آخری مجموعے ’شہزاد کے نام‘ (۲۰۰۲ء) تک بہت وسیع، تہہ دار اور پر پیچ رہا ہے۔
ان کا اسلوب بہت پرفریب ہے اور اس کی سادگی میں بہت سے رمز چھپے ہوئے ہیں۔ یہی صورتحال ان تجربوں کی ہے جو ان پر وارد ہوتے ہیں۔ انتظار حسین جانے بوجھے راستوں کا تعاقب نہیں کرتے اور بالعموم کسی نمائش جدوجہد یا ظاہری کاوش کے بغیر ان کا شعور ایسی منزلیں سر کر لیتا ہے جو عام لکھنے والوں کی نگاہ سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انتظار حسین کی تحریروں میں نوسٹیلجیا کی کیفیت کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ صفدر میر تو اس کیفیت کو انتظار حسین کے ’تخلیقی کام کی قوت محرکہ‘ سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے نوسٹیلجیا کو ماضی کے احساس یا کسی ہمہ گیر تہذیبی سیاق سے الگ کرکے اسے ’ہندوستان کے علاقہ اتر پردیش میں صرف اس جگہ‘ تک محدود کر دیتے ہیں جہاں انتظار حسین پیدا ہوئے تھے۔
یہ حقیقت بھلا دی جاتی ہے کہ دراصل انتظار حسین کے نوسٹیلجیا سے ہی مستقبلیت کے اس عنصر کی نمود بھی ہوتی ہے جو ان کے تخلیقی رویے کوماضی کے بجائے حال کی چیز بنا دیتا ہے۔ انتظار حسین انسان کی موجودہ حالت کو ایک محدود مظہر کے طور پر نہیں دیکھتے۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے ’گم شدہ زمانوں سے آنے والے زمانوں تک پھیلا ہوا‘ اور ہم جو اس آشوب کی گرمی سے عقیدوں، روایتوں، قدروں کے بہت سے سانچے پگھلتے دیکھ رہے ہیں تو اسی لئے کہ ہمارے دل میں آج سے بھی زیادہ آنے والے کل کے خطرات کا ڈر سمایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ انتظار حسین نے صرف بلند شہر، ہاپوڑ، ڈبائی، میرٹھ اور دلی کی کہانیاں نہیں لکھی ہیں اور یہ سارا قصہ صرف ایک ان کی اپنی یادداشت اور حافظے کا نہیں ہے۔ متعین حوالوں کے ساتھ لکھی جانے والی کوئی بھی کہانی صرف ایک گزرے ہوئے تجربے کے بیان پر مشتمل ہو تو وہ ’کہانی‘ نہیں رہ جاتی۔
اصل میں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کل کے معنی آج کیا ہیں اور آئندہ کیا ہوں گے اور تاریخ کو حوالہ بنا کر لکھنے والے کے لئے تو مسئلہ اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان دنوں غیر منقسم ہندوستان، تقسیم اور ہجرت کے پس منظر میں اردو کے علاوہ بھی ہماری کئی علاقائی زبانوں میں لکھنے کا چلن عام ہے۔ انڈواینگلین فکشن کے ایک معتدبہ حصے میں بھی اسی مسئلے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ انتظار حسین تاریخ کے جبر کا احساس تو رکھتے ہیں لیکن اسے اپنی بصیرت پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ ان کی کہانیوں ’گلی کوچے‘ (۱۹۵۲ء)، ’کنکری‘ (۱۹۵۱ء)، ’آخری آدمی‘ (۱۹۶۷ء)، ’شہر افسوس‘ (۱۹۷۲ء) ’کچھوے‘ (۱۹۸۱ء)، ’خیمے سے دور‘ (۱۹۸۶ء)، ’خالی پنجرہ‘ (۱۹۹۳ء)، شہزاد کے نام‘ (۲۰۰ء) اور ناولوں ’چاند گہن‘ (۱۹۵۳ء)، ’ دن اور داستان‘ (۱۹۶۲)، ’بستی‘ (۱۹۸۰ء)، ’تذکرہ‘ (۱۹۸۷ء)، ’آگے سمندر ہے‘ (۱۹۹۵ء)، کے آدھے سے زیادہ حصے میں مشترکہ ہندوستان کی تاریخ اور تقسیم کے بعد سے اب تک کی تاریخ کو ہم انتظار حسین کے بنیادی سروکار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔
لیکن کہانیوں، ناولوں سے قطع نظر، انتظار حسین کے اخباری کالموں (ذرے، ملاقاتیں، بوند بوند) اور سفرناموں (بالخصوص زمیں اور فلک اور) پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو صاف پتہ چلتاہے کہ ہماری ۱۸۵۷ء کے بعد سے اب تک کی اجتماعی زندگی نے انتظار حسین کے احساسات اور افکار کا پس منظر مرتب کیا ہے۔ ان کی حسیت پر اس پس منظر کی چھاؤں بہت گہری ہے لیکن اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ انتظار حسین تاریخ اور جیتے جاگتے واقعات کو ایک اسطور میں منتقل کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تاریخ کے اس پورے سلسلے کو انتظار حسین کبھی ایک خواب کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن ایک تمثیل کے طور پر۔ اسی لئے وہ تاریخ میں کبھی بہتے نہیں۔ معین اور معلوم واقعات اوران سے منسلک طبیعی حوالوں اور تاریخوں اور کرداروں کواپنے سامنے رکھنے کے بجائے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ا س پورے تماشے کو انسانی صورت حال کی اپنی تخلیقی تعبیر و تفہیم کے بیک ڈراپ یاسیاق کے طورپر دیکھتے ہیں۔ اس رویے کی نشاندہی خود انتظار حسین کے ایک بیان (۱۹۶۴ء) سے بھی ہوتی ہے، جس میں انتظار حسین نے کہا تھا،
’’کافکا سامنے کی چیزیں ٹھوس صورت میں پیش کرتا ہے۔ مگرپیش کرنے کا عجب طور ہے کہ ہر سامنے کی چیز ایک رمز بن جاتی ہے۔ اس کے ناول اور کہانیاں ایک نئی طرز کی ’طلسم ہوش ربا‘ ہیں مگر ہماری افسانوی روایت ایک ’طلسم ہوش ربا‘ پہلے ہی تخلیق کر چکی ہے۔ اب توہم اپنے عہد کی ’طلسم ہوش ربا‘ اسی صورت لکھ سکتے ہیں کہ پرانی ’طلسم ہوش ربا‘ اور نئی ’طلسم ہوش ربا‘ دونوں سے رشتہ جوڑیں۔‘‘
انتظار حسین کو جاننے اور سمجھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حقیقت پسندی کا افسانہ لکھنے کے لئے جو رویہ درکار ہوتا ہے، بہت مختلف ہے اور انتظار حسین کی طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان کی تحریریں اپنے نہایت مستحکم معاشرتی حوالوں اور اپنی مقامیت اور ارضیت کے باوجود تاریخی دستاویز کا اعتبار نہیں رکھتیں۔ انہیں ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح ’امراؤ جان ادا‘، ’گئودان‘، ’آگ کا دریا‘ کو پڑھتے ہیں۔ انتظار حسین کے پچاس برس کی یادوں پر مشتمل کتاب ’چراغوں کا دھواں‘ لگ بھگ چار برس پہلے (۱۹۹۹ء) میں سامنے آئی تھی۔ سب کا سب دیکھی بھالی باتوں کا لیکھا جوکھا۔ مگر اس روداد میں بھی ایک نئے طلسم ہوش ربا کی مہک شامل تھی۔ اپنے تجربے میں آنے والے جن کرداروں کا حال انتظار حسین نے اس کتاب میں کسی طرح کی جذباتیت کے بغیر ’شانت سبھاؤ کے ساتھ‘ بہت ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا ہے، وہ حقیقی ہونے کے بعد بھی ایک حد تک افسانوی شخصیتوں کا تاثر قائم کرتے ہیں۔
ان کرداروں کی موجودگی سے ہماری اجتماعی زندگی کیسی بھری پُری بارونق تھی۔ کتنی منور اور رنگا رنگ تھی اور ان کے چلے جانے سے یہ سارا منظر نامہ کتنا پھیکا، خالی خالی سا، غیردل چسپ اور غم آلود ہو گیا، اس کا نقشہ آنکھوں میں گھوم جاتاہے۔ بہ ظاہر انتظار حسین کوئی اخلاقی فیصلہ نافذ نہیں کرتے، کوئی بیان نہیں دیتے، تجزیہ نہیں کرتے، لیکن انسانی صورت حال کی دھوپ چھاؤں اور ہماری بگڑتی بکھرتی ہوئی دنیا کے اندھیرے اجالے کا ایک طلسم خودبخود اس طرح مرتب ہوتا جاتا ہے کہ ہم چور آنکھوں سے اپنے آپ کو بھی دیکھنے لگتے ہیں اور اپنی دنیا اور زمانے کو بھی۔
انتظار حسین کی تحریریں جس گہری، پائدار سطح پر اپنے قاری میں پشیمانی، افسردگی، اذیت اور خوف کا احساس جگاتی ہیں، اس سطح پر ہمارے زمانے کے بس معدودے چند لکھنے والوں کی رسائی ممکن ہو سکی ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کی تخلیقی تعبیر کا بوجھ صرف ایسے لکھنے والے سنبھال سکتے ہیں جن کی روحیں اضطراب آسا اور اندوہ پرور ہوں اور جو نڈھال اور خراب ہونے کے باوجود زندہ رہنے کی اس روش اور ان آداب کو خاطر میں نہ لاتی ہوں جن کے دم سے ابتذال اور بدمذاقی کا بازار چاروں طرف گرم ہے۔
انتظار حسین اپنی دھن میں رہتے ہیں اور اپنی شرطوں اور ترجیحوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے گردوپیش کی زندگی کا سیلاب ان کے اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے تھم جاتا ہے۔ یہی حال انتظار حسین کی عام شخصیت کاہے، ایک حد تک مقفل اور مرموز، جس کے بھید آسانی سے نہیں کھلتے، جو اپنے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے اخفا اور روپوشی کا گیان بھی رکھتی ہے۔۔۔ ان کی کہانیاں اسی لئے زمین دوز کہانیاں ہیں، اوپر سے خاموش، ٹھنڈی، شانت مگر اندر سے بہت پر شور، ہلچل سے بھری ہوئی اور طوفانی۔